Jan 29 2015
Khutbat Hakeemm ul ummat 29-Jan-2015
Khutbat Hakeemm ul ummat 29-Jan-2015
Hazrath Maulana Shah Mufti Mohammed Nawal ur Rahman Sahab Damat Barkatuhum

Jan 29 2015
Hazrath Maulana Shah Mufti Mohammed Nawal ur Rahman Sahab Damat Barkatuhum

Jan 26 2015
دنیا کی وہ تمام عظیم الشان قومیں جنہوں نے دنیا میں کوئی بڑا کام کیا ہے یا جو دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتی ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے پورے نظامِ ہستی کو کسی ایک قانون پر مبنی کریں اور اپنی تمام منتشر قوتوں کو کسی ایک اصول کے تحت مجتمع کریں، زندگی کے سینکڑوں شعبے اور بقائے ہستی اور ترقی کے ہزارہا شاخ در شاخ اعمال جو دیکھنے میں تمام تر منتشر، پراگندہ، متفرق اور ایک دوسرے سے الگ نظر آتے ہیں، ان سب کے درمیان ایک واحد نظام، ایک متحدہ اصول اور ایک مشترکہ جامعیت پیدا کریں، جن کا شیرازہ ان متفرق و پراگندہ اوراق کو ایک منظم کتاب بنادے۔
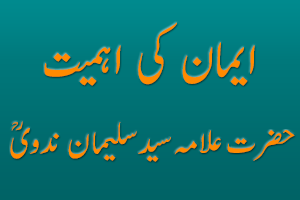
دنیا جب سے بنی ہے تب سے آج تک ہزارہا قومیں پیدا ہوئیں اور مریں؛ لیکن کسی قوم نے اس وقت تک ترقی نہیں کی جب تک کہ اس کے اندر اس کی زندگی کا کوئی واحد نظام نہیں پیدا ہوا، اور کسی واحد متخیلہ نے ان کے اندر یہ اہمیت نہیں پیدا کرلی ہے کہ وہ اس کے تمام افراد کی زندگی کی غرض و غایت اور اس کے تمام اعمال کا مرکز و مرجع اور جہت و قبلہ نہ بن گیا ہو، وہی واحد متخیلہ بڑھ کر واحد جماعت اور اس سے بھی زیادہ پھیل کر ایک واحد ملت کی تخلیق و تکوین کرتا ہے۔
ہم اس کو ایک مثال میں سمجھانا چاہتے ہیں، روم کی سلطنت کا آغاز گاؤں سے ہوا اور رفتہ رفتہ یہ نقطہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ صدیق میں ایک عظیم الشان سلطنت بن گئی، اس دائرہ کا نقطۂ خیال، مرکزِ اتحاد، جہتِ اشتراک، اساسِ جامعیت، رومیت قرار پائی، جس نے رومیت کے اصول کو تسلیم کیا اس کو شہرِ روم کے باشندوں کے حقوق عطا ہوئے اور جس نے قبول نہ کیا یا جس کو یہ شرف خود رومیوں نے عطا نہیں کیا وہ ان حقوق سے محروم رہا، صدیوں تک یہ رومیت رومی قوم کی زندگی کا شعلۂ حیات رہی اور اس کی روشنی سے پورا رومن امپائر اسپین سے لے کر شام تک جگمگاتا رہا، مگر جیسے جیسے یہ روشنی ماند پڑتی گئی اندھیرا چھاتا گیا اور جیسےسے رومی عمارت کی یہ مستحکم بنیاد کمزور پڑتی گئی ڈہتی گئی، یہاں تک کہ ایک دن یہ عمارت گر کر زمین کے برابر ہوگئی۔
الغرض قوموں کی موت و حیات کسی ایک ’’متخیلہ‘‘ کی موت و حیات پر موقوف ہے، جس کی زندگی سے زندگی اور جس کی موت سے موت ہے، گذشتہ جنگ میں اور اس جنگ میں بھی آپ سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں کہ انگریز، جرمن یا جرمن انگریز سے لڑ رہے ہیں، نہیں!انگریزیت جرمنیت سے یا جرمنیت انگریزیت سے لڑ رہی تھی اور لڑ رہی ہے، قوم قوم سے نہیں لڑ رہی ہے بلکہ ایک یقینی تخیل دوسرے یقینی تخیل سے لڑتا ہے۔
قوم کی زندگی کا وہ یقینی تخیل اس کے تمام کاموں کی اساس و بنیاد بن جاتا ہے، پوری قوم اور قوم کے تمام افراد اس ایک نقطہ پر جمع ہوجاتے ہیں، وہ نقطۂ ماسکہ ان کی پوری زندگی کا محور بن جاتا ہے، اسی ایک تخیل کا رشتہ منتشر افراد کو بھائی بھائی بناکر ایک قوم کے مشترکہ افراد ترتیب دیتا ہے اور ایک واحد، متحد، منظم اور قوی قوم بناکر کھڑا کردیتا ہے۔
جب کبھی دو قوموں کا مقابلہ ہوگا تو ہمیشہ اس کو فتح ہوگی جس کا نقطۂ تخیل زبردست ہوگا اور جس کے افراد اس رشتۂ حیات میں سب سے زیادہ مستحکم بندھے ہوں گے اور جو اس مشترک اساس و بنیاد پر سب سے زیادہ متفق و متحد ہوں گے، عربوں نے اسی قوت سے قیصر و کسریٰ کو شکستِ فاش دی، عربوں کے پاس ایرانیوں کے خزانے اور نہ رومیوں کے اسلحہ تھے، مگر ان کے پاس وہ قوتِ ایمانی تھی جس سے ایرانی اور رومی محروم تھے۔
جب کوئی قوم تنزّل پذیر ہوتی ہے تو اس کی وہی قوتِ ایمانی کمزور ہوجاتی ہے، اس کی وہی مشترک اساس و بنیاد منہدم ہونے لگتی ہے اور قوم کی زندگی کا مقصد اس مشترکہ قومی غرض و غایت سے ہٹ کر اپنے اپنے نفس، اپنے اپنے خاندان، اپنی اپنی جماعت میں بٹ جاتا ہے، اس لئے اس میں قومی خائن پیدا ہوتے ہیں جن کے پیشِ نظر اس مشترکہ جامعیت کے فوائد و نقصانات کے بجائے خود اپنی ذات و خاندان کا فائدہ و نقصان ہوتا ہے۔
مٹھی بھر انگریزوں نے ہندوستان کے روپئے سے اور ہندوستان ہی کے سپاہیوں سے خود ہندوستان کو فتح کیا، حالانکہ اس وقت پورے ملک میں اودھ، روہیل کھنڈ، بنگال، مرہٹہ، میسور اور حیدرآباد کی ایسی عظیم الشان طاقتیں تھیں جن کے بس میں تھا کہ انگریزوں کو پوری طرح شکست دے دیں، مگر ایسا نہ ہوسکا، اس لئے کہ انگریزوں کے سامنے ایک متحدہ و مشترکہ تخیل تھا جس پر پوری قوم متفق تھی، جو انگریز جہاں بھی تھا چاہے وہ سپاہی ہو، یا گودام کا کلرک ہو، یا سوداگر ہو، یا ڈاکٹر ہو، یا جنرل ہو یا گورنر ہو ہر ایک کے سامنے ایک ہی بلند مقصد تھا اور وہ انگلستان کی سربلندی اور عظمت، لیکن ہندوستانیوں کے سامنے باوجود طاقت و قوت کے کوئی ایک متحدہ غرض، مشترکہ جامعیت، واحد اساسِ کار اور متفقہ بنیادِ عمل نہ تھی جس کا بچاؤ، جس کی حفاظت اور جس کا اِعلاء پوری قوم کی غرض و غایت اور بنیاد و اساس ہوتی، ہر نواب، ہر رئیس، ہر سپہ سالار، ہر سپاہی اور ہر نوکر کا مقصد اپنی فکر اور اپنی ترقی تھی، اس حالت میں نتیجہ معلوم۔
اب ایک اور حیثیت سے نظر ڈالئے، دنیا کی ہر متمدن قوم کے پورے نظامِ زندگی کا ایک اصل الاصول ہوتا ہے، فرض کرو کہ آج روسی بالشوسٹ کے سارے نظام کا ایک واحد نقطۂ خیال ہے، اور وہ سرمایہ داری کی مخالفت ہے جو اس نظام کی اصل اساس ہے، اب جس قدر اس نظام کی شاخیں، شعبے، صیغے اور کام ہیں سب ایک اصل الاصول یعنی ’’سرمایہ داری کی مخالفت‘‘ پر مبنی ہیں، اسی طرح ہر ترقی یافتہ قوم کے تمدن اور نظامِ ہستی کا ایک اصولی نقطہ ہوتا ہے جس کے تحت میں اس تمدّن اور نظامِ ہستی کے تمام شعبہ اور فروع ہوتے ہیں۔
اسی طرح آج انگریزی جد و جہد کی بنیاد، انگریزی سرمایہ داری، امریکن تمدّن کی بنیاد امریکن سرمایہ داری، نازی تمدّن کی بنیاد جرمن قوم کی سربلندی اور فسست کی بنیاد پرانی رومی قیصریت کی دوبارہ تعمیر پر ہے، اگر کسی تمدّن اور نظام کا یہ سرا نکال دیا جائے تو اس تمدن کے تمام اجزاء اور اس نظام کے تمام شعبے بے معنیٰ، بے سود اور بے اساس ہوکر رہ جائیں، اور چند ہی روز میں وہ تمام سر رشتے تارِ عنکبوت ہوکر نابود ہوجائیں، اسی لئے ہر قومی تمدّن اور نظامِ ملت کو سمجھنے کے لئے اس کے اس اساسِ کار، سر رشتۂ خیال اور اصل الاصول کو سمجھنا چاہئے، جب تک وہ سِرا ہاتھ نہ آئے گا اس نظامِ ملت کا الجھاؤ سلجھ نہیں سکتا۔
اس نقطہ کو خوب سمجھ لینا چاہئے کہ دنیا میں گو ہزاروں ملتیں اور قومیتیں ہیں لیکن ان میں سے ہر ایک ملت و قومیت کا اصل انفرادی تشخص اور امتیازی وجود اس کے گوشت پوست، ہڈی اور رنگ و روغن سے نہیں یہ اوپری سطح اور ظاہری قشر پر کے نشانات اور خطوط ہیں، ان کا اصل انفرادی اور مستقل تشخص اور امتیازی وجود ان ایمانیات اور یقینیات سے ہے جو ہر ایک کے دل میں بسے اور ہر ایک کے رگ و ریشہ میں رچے ہوئے ہیں۔
آج ہندوستان میں ہندو، مسلمان، عیسائی، پارسی، جین، سکھ اور ہزاروں قومیں آباد ہیں، شکل و صورت اور رنگ و روپ کے لحاظ سے ان میں کوئی تفاوت نہیں، اگر ہے تو ہر ایک کے اس متخیلہ میں ہے جس سے اس کی ملت کی تعمیر ہوئی ہے، اس لئے کسی ملت کے متخیلہ کو بدل دینے کے معنیٰ اس ملت کو مٹادینے کے مترادف ہے، دنیا میں جو کمزور قومیں فناء ہوئی ہیں ان کی صورت یہی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنا متخیلہ ایمانی چھوڑ کر کسی دوسری طاقتور قوم کے متخیلۂ ایمانی کو قبول کرلیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قوم مٹ گئی اور دوسری قوم میں ضم ہوکر وہ خود فناء ہوگئی، ہندوستان کے یونانی، سیتھین اور بودھ کیا ہوئے؟ ایرین ہندوؤں میں سما گئے، ایران کے مجوسی کدھر گئے؟ مسلمانوں میں مل گئے، مصر کے قبطی کہاں گئے؟ عربوں میں شامل ہوگئے، سسلی اور اسپین کے عرب کیا ہوئے؟ اٹلی اور اسپین والوں میں گھل گئے۔
کسی قوم و ملت کی اس تعمیری حقیقت سے باخبر رہنا صرف اس لئے ضروری نہیں کہ وہ ہے اور وہ اس سے بنی ہے، بلکہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ اس کی تجدید و اصلاح کی جب کبھی ضرورت پیش آئے تو اس حقیقت کا واقف اسی کے ذریعہ سے اس کی تجدید و مرمّت کرے، اس کی وہ تعمیری حقیقت وہ ساز ہوتا ہے جس کے چھیڑنے سے اس قومیت و ملت کا ہر تار اپنی جگہ پر حرکت کرنے لگتا ہے، اہلِ توحید کے لئے توحید کی آواز اہلِ صلیب کے لئے صلیب کی پکار، گاؤ پرست کے لئے گاؤ کی آواز سحر و طلسم کا حکم رکھتی ہے، جس سے ایک ایک لمحہ میں قوم کی قوم میں جان پڑ جاتی ہے اور سست و ناکارہ قوم بھی کروٹیں بدلنے لگتی ہے، اور آواز کی طاقت کے مطابق سر گرمِ عمل ہوجاتی ہے۔
فرض کرو دنیا میں آج چالیس کروڑ کی تعداد میں ایک ملت آباد ہے جس کا نام مسلمان ہے، اس ملت کی حقیقت کیا ہے؟ توحیدِ الٰہی اور رسالتِ محمدیؐ پر ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر کوئی اس ملت کی حقیقتِ تعمیری کو مٹا ڈالے تو یہ چالیس کروڑ ملت واحدہ چالیس کروڑ قومیتوں میں منقسم ہوکر دم کے دم میں فناء ہوجائے گی اور یہ چالیس کروڑ افراد کا کارواں جو ایک صدائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جرس پر حرکت کر رہا ہے، اب اس کی حرکت کے لئے مختلف آوازوں کے چالیس کروڑ جرسوں کی ضرورت پیش آئے گی جس سے دنیا کی قوموں کا تصادم بجائے کم ہونے کے حدّ قیاس سے زیادہ بڑھ جائے گا اور ان کے باہمی جنگ و جدول کو کوئی ایک متحدہ آواز روک نہیں سکتی۔
الغرض ملت کی یہ تعمیری حقیقت ہر ملت کی روح ہوتی ہے، اس کی بقاء سے اس کی زندگی اور اس کی موت سے اس کی فناء ہوتی ہے، یہی ملت کے جسم کا گرم خون ہے جس سے رگ رگ میں زندگی کی لہر دوڑتی ہے اور سعی و عمل کی قوت بیدار ہوتی ہے۔
کسی قوم کی اس اساسِ ملت اور بنیادِ تعمیر سے ہٹ کر جب کبھی اس تجدید کا کام کیا جائے گا تو وہ ساری کوشش بیکار جائے گی، فرض کرو کہ ایک ہندو قوم ہے اس کی قومیت کی بنیاد وہ خاص تخیلات و جذبات ہیں جو ہزار سال سے اس میں پیدا ہوکر اس کی حقیقت کے اجزاء بن گئے ہیں، ذات پات، چھوت چھات، گائے اور گنگا وہ مسالے ہیں جن سے اس کی قومیت کی تعمیر ہوئی ہے، بودھ کے عہد سے آج تک مختلف وقتوں میں بیسیوں ریفارمر اس قوم میں پیدا ہوئے جنہوں نے اس قوم کی ماہیت کے ان اجزاء کو بدل دینا چاہا، مگر یہ کیا آج تک ممکن ہوا؟ اور جب کبھی اس آواز میں عارضی کامیابی ہوئی تو بودھ، جین، کبیر پنتھی اور سکھ قومیں الگ الگ بن گئیں، مگر ہندو قومیت اپنی جگہ پر قائم رہی۔
مسلمانوں میں اسلامی حکومت کے زوال کے بعد سے آج تک بیسیوں تحریکیں مسلمانوں کی تجدید اور نشأۃ ثانیہ کے نام سے اٹھیں اور پھیلیں، مگر جو کامیابی مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کو حاصل ہوئی اور اس نے مسلمانوں کی ذہنی و عملی قویٰ کو بیدار کرنے میں جو عظیم الشان کام کیا، اس کی صرف یہی وجہ تھی کہ وہ تجدید اسلام کے اصل و اساس، نظامِ حقیقی کو سامنے رکھ کر شروع کی گئی تھی اور اس کے بعد بھی موجودہ زمانہ تک اسی تحریک کو فروغ ہوسکا جو اسی اساسِ ملت کے نام سے پیش کی جاتی رہی، اس کامیابی کا عارضی اور ہنگامی ہونا در اصل خود کارکنوں اور تحریک کے علم برداروں کے عارضی یقین اور ہنگامی ایمان کا نتیجہ ہے۔
اب اس تشریح کے بعد اس کے تسلیم کرنے میں کسی کو عذر نہ ہوگا کہ دنیا میں کوئی ترقی یافتہ قوم یا ترقی چاہنے والی قوم ممکن ہی نہیں جس کے پاس چند ایمانیات نہ ہوں یا یوں کہو کہ چند اصولِ کار، اصولِ حیات یا اصولِ نظام نہ ہوں، جن سے اس کی قومیت کی تخلیق ہوتی ہے اور جن سے اس کی ملت و تمدن و حیاتِ اجتماعی کی عمارت قائم ہوتی ہے اور جو اس کے منتشر افراد کے درمیان رشتۂ اشتراک کا کام دیتے ہیں، اور جن کے تحت میں اس قوم کے نظامِ حیات کے تمام شعبے مکمل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کافر و مشرک قومیں بھی اس سے خالی نہیں، ان کے بھی تمام اعمال و افعال ان کے چند یقینی تخیلات اور عقائد کے تحت ہی میں آجاتے ہیں، اس حالت میں یہ کہنا کہ ایمانیات کے بغیر ترقی کے حسنِ عمل یا انسانیت کی نیکئ کردار کا وجود ہوتا ہے، حقائق سے نامحرمی کا ثبوت ہے، ایمان کے بغیر حسنِ عمل اور نیکئ کردار کیا بلکہ نفسِ عمل اور نفسِ کردار ہی کا وجود ممکن نہیں، اب اگر بحث ہوسکتی ہے تو اس میں نہیں کہ ایمانیات کے بغیر حسنِ عمل اور نیکی کردار کا وجود ہوسکتا ہے یا نہیں؟ بلکہ اس میں کہ ان ایمانیات کے تحت میں حسنِ عمل اور نیکی کردار کا وجود زیادہ بہتر ہوسکتا ہے، یا ان ایمانیاں کے تحت میں؟ لیکن یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ کسی ’’ایمان‘‘ کے بغیر کوئی عمرل، کسی نظامِ حیات کے بغیر کوئی بلند کارنامۂ حیات اور کسی بنیاد کے بغیر کوئی مستحکم عمارت قائم ہوسکتی ہے، آپ اس کا نام انسانیت رکھیں، قومیت رکھیں، وطنیت رکھیں، بالشوزم رکھیں، بت پرستی رکھیں یا توحید یا خدا شناسی رکھیں، جو چاہے رکھیں اور جو چاہے قرار دیں، بہر حال یہ مقدمہ اپنی جگہ پر مسلَّم ہے کہ ’’ایمان کے بغیر عملِ صالح کا وجود ممکن ہی نہیں‘‘، اب سوال یہ ہے کہ ہمارا وہ اساسی خیال جس پر ہماری ملت کی بنیاد ہو اور جو ہمارے تمام اعمال کا سرچشمہ بنے کیا ہونا چاہئے؟
دنیا کی قوموں نے اساسِ ملت کی بنیاد جغرافیائی حدود اور نسلی خصوصیت کو قرار دیا، رومیوں کی ہزار سالہ حکومت رومی وطنیت کے سہارے پر قائم رہی، ہندوؤں، پارسیوں اور یہودیوں کی قومیت نسلی امتیاز پر مبنی ہے، یورپ کی موجودہ قومیتیں، نسل و وطن کی دوہری دیواروں پر کھڑی ہیں، لیکن خود غور کرو کہ جغرافیائی حدود اور نسلی و وطنی خصوصیات نے قوموں کو کتنا تنگ، محدود خیال اور متعصب بنادیا ہے، دنیا کی اکثر خونریزیاں، لڑائیاں اور قومی منافرتیں انہی جذبات نے پیدا کی ہیں، قدیم تاریخ میں ایران و روم کی صد سالہ جنگ اور خود یورپ کی گذشتہ عالمگیر جنگ جس میں انسانوں نے انسانوں کو درندوں کی طرح چیرا اور پھاڑا، اسی نسلی و وطنی جذبات کی شعلہ افروزی تھی اور آج کا خونی تماشا بھی اسی جذبہ کا نتیجہ ہے۔
یہ نسلی اور وطنی افتراق قوموں کے درمیان و ہ خلیج ہے جس کو انسانوں کے ہاتھ کبھی پاٹ نہیں سکتے، نہ تو فطرۃً کسی نسل و قومیت کا کوئی پیدا شدہ انسان دوسری نسل و قومیت میں داخل ہوسکتا ہے اور نہ ایک مقام کا پیدا شدہ دوسرے مقام کا پیدا شدہ بن سکتا ہے، نہ کالا گورا بن سکتا ہے، نہ گورا کالا اور نہ فرنگی زنگی بن سکتا ہے، نہ زنگی فرنگی، نہ جرمن کو انگریز بنایا جاسکتا ہے اور نہ انگریز کو جرمن، نہ افغانی ہندوستانی بن سکتا ہے اور نہ ہندوستانی افغانی، آج پولینڈ کے کھنڈروں سے لے کر رومانیا کے روغنی چشموں تک جو زمین خون سے لالہ زار ہے اس کا سینہ کیا اسی نسلی و وطنی خونخواریوں سے داغ دار نہیں؟
غرض نسل و وطن کے دائرے اس مضبوطی سے فطرۃً محدود ہیں کہ ان کے اندر تمام دنیا تو کیا، چند قوموں کے سمانے کی بھی وسعت نہیں ہے، ان دونوں کے جذبات و احساسات صرف ایک مختصر و محدود قوم کی جامعیت کا کام دے سکتے ہیں، کسی عالمگیر امن و صلح اور انسانی اخوّت و برادری کی بنیاد اس پر رکھی ہی نہیں جاسکتی۔
پھر ان دونوں محدود تصورات کے ذریعہ سے اگر انسانوں میں کچھ شریفانہ جذبات پیدا ہوسکتے ہیں تو وہ انہی تنگ جغرافیائی اور نسلی دائروں تک محدود رہیں گے اور کبھی تمام دنیا کے اس کے اندر سماجانے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، علاوہ ازیں ان اساسی تصورت کے ذریعہ جن بلند انسانی اخلاق اور کیرکٹر کا پیدا کرنا مقصود ہے، ان میں سے صرف نسل و وطن کی حفاظت کی خاطر شجاعت، ایثار و قربانی کے جذبات پیدا ہوسکتے ہیں ،مگر عمومی نیکی، تواضع، خاکساری، رحم و شفقت، عفت و عصمت، صدق اور امانت و دیانت وغیرہ سینکڑوں ایجابی اور سلبی اخلاق ہیں جو ان کے ذریعہ نہ کبھی پیدا ہوئے ہیں اور نہ ہوسکتے ہیں۔
آج کل یورپ کی تمام جنگ و جدل اور باہمی ہنگامہ آرائی اور تقابل کا وہ پتھر جس سے ان کی دولت اور تہذیب و تمدن کا شیشہ چور چور ہو رہا ہے یہی تنگ و محدود وطنیت و قومیت کا عقیدہ ہے، یہ وہ دیوتا ہے جس پر یورپ کی تمام قومیں بھینٹ چڑھ رہی ہیں، ہر قوم کے تمام دولت مندوں کی دولتیں، تمام عالموں کا علم، تمام سائنس والوں کی سائنس، تمام صنّاعوں کی صنعتیں، تمام موجدوں کی ایجادیں، اپنی قوم کے سواء دنیا کی دوسری انسانی قوموں کی گرفتاری، محکومی، بربادی اور ہلاکت میں صرف ہورہی ہیں۔
آج نازازم اور فسزم کا دور ہے، جس نے ایک بدترین مذہب کی صورت اختیار کرلی ہے، جس میں ہر قسم کی حیوانی قوّت کی نمائش، ہر قسم کی ہلاکت اور انسانی بربادی کا مہیب ترین منظر اور قوت کے دیوتا کے سامنے ہر اخلاقی اور قانونی آئین کی قربانی کا تماشا سب کے سامنے ہے، یہ جو کچھ ہے یہ وہی قومیت اور وطنیت کی خونخوارانہ بُت پرستی کا عبرتناک نظارہ ہے، جس سے نوعِ انسانی کی کسی بھلائی کی توقع نہیں ہوسکتی۔
سوشلزم اور بالشوزم اور دوسرے اقتصادی خیالات سے بھی بھلائی کی توقع نہیں کہ اس نے خود انسانوں کو سرمایہ دار و غیر سرمایہ دار دو مختلف حصوں میں تقسیم کرکے وہ سب کچھ کیا ہے اور کرنا چاہتی ہے جو کبھی کسی مذہب اور مذہبی محکمۂ تفتیش نے انجام دیا ہے، قوموں کے ساتھ ان کی ناانصافی کا تماشا آج بھی دنیا ترکستان سے لے کر فین لینڈ تک دیکھ رہی ہے، اگر زبردستی کوئی بری چیز ہے تو مذہب سے زبردستی روکنا بھی اتنی ہی بری چیز ہے جتنا زبردستی سے کسی مذہب کو پھیلانا، اگر مسلمانوں کا گرجاؤں کا توڑنا اور عیسائیوں کا مسجدوں کا منہدم کرنا ناجائزہے تو ملحدوں کا ان دونوں کو مسمار کرنا بھی ناجائز ہے۔
پھر ان تخیلات میں جن کی بنیاد محض پیٹ اور دولت کی منصفانہ تقسیم ہے، کسی اخلاقی نصب العین بننے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، اسی لئے ان کا محدود اقتصادی نظریہ پورے نظامِ ہستی اور نظامِ زندگی کا معمہ حل نہیں کرسکتا۔
ان سب کے ماوراء یہ ہے کہ ضرورت تو یہ ہے کہ نسلیت و وطنیت کے تنگ دائروں سے نکل کر جس عمومی تصور کو اساسِ ملت بنایا جائے، ان میں بقاء اور دوام کی صلاحیت ہو، سوسائیٹیاں اور جماعتیں جن کی بنیاد کسی مادّی خود غرضی اور منفعت اندوزی پر رکھی جائے وہ ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتیں، چنانچہ جب سے دنیا بنی ہے خدا جانے مادّی اغراض کی بناء پر کتنی جماعتی اور مجلسیں قائم ہوئیں اور مٹ گئیں، انجمنیں روز بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں، اور سوسائیٹیاں روز پیدا ہوتی ہیں اور مرتی ہیں، ایسی ناپائیدار اور سطحی چیزیں جامعیتِ ملت کی بنیاد اور اساس نہیں بن سکتیں اور نہ وہ ہمارے نظامِ حیات کا اصول اور معیار قرار پاسکتی ہیں۔
غرض عالمگیر اور دائمی اساسِ ملت اور صحیح بنیادِ عمل بننے کے لئے ضروری ہے کہ جو چیز اساس و بنیاد قرار دی جائے اس میں حسبِ ذیل خصوصیتیں ہوں:
(۱) وہ کوئی مادّی غرض و غایت کی چیز نہ ہو جو ہمیشہ بدل جاتی رہے۔
(۲) وہ کوئی محدود وطنی، نسلی بُت نہ ہو جو اپنے نسل و وطن سے باہر جاکر زندہ نہ رہ سکے۔
(۳) وہ قومی، نسلی اور وطنی منافرتوں اور تفرقوں کو بیخ و بنیاد سے اکھاڑ کر عالمگیر اتحاد اور اخوت کی بنیاد ڈال سکے۔
(۴) وہ تخیل عقیدہ بنکر ہمارے نیک افعال کا محرّک اور بُرے افعال کا مانع بنے، وہ انسانوں کو نیکی کے لئے اُبھارے اور برائی سے روک سکے۔
(۵) وہ ایک ایسا دائمی صحیح اور سچا عقیدہ ہو جس کو مان کر اس برادری میں داخل ہونے میں کسی کو دقت نہ ہو۔
(۶) وہ ایک طرف اپنے بندوں اور اپنے خالق کے ساتھ گرویدگی اور بندگی کا تعلق پیدا کرے اور دوسری طرف اپنی ہم جنس مخلوقات کےساتھ محبت اور ادائے حقوق کا جذبہ پیدا کرے۔
ان چند عقلی مبادی کے ثبوت کے بعد اب آئیے اسلام کے اصول عقائد و مبادی کا جائزہ لیں، اسلام میں جس حقیقت کو عقائد کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ در حقیقت یہی چند ذہنی اصول و مبادی ہیں جو جماعت کا کریڈ اور تمام انسانی افکار و خیالات کی بنیاد و اساس ہیں، ان کے تمام افعال، اعمال اور حرکات اسی محور کے گرد چکر کھاتے ہیں، یہی وہ نقطہ ہے جس سے انسانی عمل کا ہرخط نکلتا ہے اور اس کے دائرۂ حیات کا ہر خط اسی پر جاکر ختم ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے تمام افعال اور حرکات ہمارے ارادہ کے تابع ہیں، ہمارے ارادہ کا محرک ہمارے خیلات اور جذبات ہیں، اور ہمارے خیالات اور جذبات پر ہمارے اندرونی عقائد حکومت کرتے ہیں، عام بول میں انہیں چیزوں کی تعبیر ہم ’’دل‘‘ کے لفظ سے کرےت ہیں، اسلام کے معلم نے بتایا کہ انسان کے تمام اعضاء میں اس کا دل ہی نیکی اور بدی کا گھر ہے، فرمایا:
انسان کے بدن میں گوشت کا ٹکڑا ہے جو اگر درست ہے تو تمام بدن درست ہے اور اگر وہ بگڑ گیا تو تمام بدن بگڑ گیا، ہاں وہ ٹکڑا دل ہے۔قرآن پاک نے دل (قلب) کی تین کیفیتیں بیان کی ہیں، سب سے پہلے قلبِ سلیم (سلامت رَو دل) ہے، جو ہر گناہ سے پاک رہ کر بالطبع نجات اور سلامت روی کے راستہ پر چلتا ہے، دوسرا اس کے مقابل میں قلبِ اثیم (گنہگار دل) ہے، یہ وہ ہے جو ہمیشہ گناہوں کی راہ اختیار کرتا ہے، اور تیسرا قلبِ منیب (رجوع ہونے والا دل) ہے، یہ وہ ہے جو اگر کبھی بھٹکتا اور بے راہ بھی ہوتا ہے تو فوراً نیکی اور حق کی طرف رجوع ہوجاتا ہے۔
غرض یہ سب نیرنگیاں اسی ایک بے رنگ ہستی کی ہیں جس کا نام دل ہے، ہمارے اعمال کا ہر محرم ہمارے اسی دل کا ارادہ اور نیت ہے، اسی بھاپ کی طاقت سے اس مشین کا ہر پُرزہ چلتا اور حرکت کرتا ہے، اسی لئے آپؐ نے فرمایا:
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ۔ (صحیح بخاری:آغازِ کتاب) تمام کاموں کا مدار نیت پر ہے۔
اسلام نے چونکہ علم و عمل، تصور اور فعل، عقلیت اور عملیت میں لزوم ثابت کیا ہے اور عقائد کے اتنے ہی حصہ کا یقین و اقرار ضروری قرار دیا جو عمل کی بنیا اور اخلاق و عبادات کی اساس قرار پاسکے اور دل کی اصلاح و تزکیہ میں کام آسکے، اور اسی لئے اس نے عقائد کے فلسفیانہ الجھاؤ اور تصوّرات و نظریات کی تشریح و تفصیل کرکے عملیت کو برباد نہیں کیا، چند سیدھے سادے اصول ہیں جو تمام ذہنی سچائیوں اور واقعی حقیقتوں کا جوہر اور خلاصہ ہیں اور انہی پر یقین کرنے کا نام ایمان ہے، اور صریح الفاظ میں اس ایمان کے صرف پانچ اصول تقلین کئے: (۱) خدا پر ایمان، (۲) خدا کے فرشتوں پر ایمان، (۳) خدا کے رسولوں پر ایمان، (۴) خدا کی کتابوں پر ایمان، اور (۵) اعمال کی جزاء اور سزاء کے دن پر ایمان۔
(۱) اللہ تعالیٰ پر ایمان کہ وہ اس دنیا کا تنہاء خالق اور مالک ہے اور ہر ظاہر و باطن سے آگاہ ہے تاکہ وہی ہمارے تمام کاموں کا قبلۂ مقصود قرار پاسکے اور اس کی رضا جوئی اور اس کی مرضی کی تعمیل ہمارے اعمال کی تنہاء غرض وغایت ہو، اور ہم جلوت کے سواء خلوت میں بھی گناہوں اور برائیوں سے بچ سکیں، اور ہر نیکی کو اس لئے کریں ار وہر برائی سے اس لئے بچیں کہ یہی ہمارے خالق کا حکم ہے اور یہی اس کی مرضی ہے، اس طرح اعمال ناپاک اغراض اور ناجائز خواہشات سے مبرّا ہوکر خالص ہوسکیں، اور جس طرح ہمارے جسمانی اعضاء گناہوں سے پاک ہوں، ہمارا دل بھی ناپاک خیالات اور ہوا و ہوس کی آمیزش سے پاک ہو اور اس کے احکام اور اس کے پیغام کی سچائی پر دل سے ایسا یقین ہو کہ ہمارے ناپاک جذبات، ہمارے غلط استدلالات، ہماری گمراہ خواہشیں بھی اس یقین میں شک اور تذبذب پیدا نہ کرسکیں۔
(۲) خدا کے رسولوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ خدا کے ان احکام اور ہدایات اور اس کی مرضی کا علم انہی کے واسطے سے انسانوں کو پہنچا ہے، اگر ان کی صداقت، سچائی اور راستبازی کو کوئی تسلیم نہ کرے تو پیغامِ ربانی اور احکامِ الہٰی کی صداقت اور سچای بھی مشکوک و مشتبہ ہوجائے اور انسانوں کے سامنے نیکی، نزاہت اور معصومیت کا کوئی نمونہ موجود نہ رہے، جو انسان کے قوائے عملی کی تحریک کا باعث بن سکے، پھر اچھے اور بُرے، صحیح اور غلط کاموں کے درمیان ہماری عقل کے سواء ہمارے جو جذبات کی محکوم ہے کوئی اور چیز ہمارے سامنے ہماری رہنمائی کے لئے نہیں ہوگی۔
(۳) خدا کے فرشتوں پر بھی ایمان لانا واجب ہے کہ وہ خدا اور اس کے رسولوں کے درمیان قاصد اور سفیر ہیں، مادیت اور روحانیت کے مابین واسطہ ہیں، مخلوقات کو قانونِ الٰہی کے مطابق چلاتے ہیں اور ہمارے اعمال و افعال کے ایک ایک حرف کو ہر دم اور ہر لحظہ ریکارڈ کرتے جاتے ہیں، تاکہ ہم کو ان کا اچھا یا بُرا معاوضہ مل سکے۔
(۴) خدا کے احکام و ہدایات جو رسولوں کے ذریعہ انسانوں کو پہنچائے گئے ہیں ان کو دور دراز ملکوں اور آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے لئے ضروری ہوا کہ وہ تحریری شکلوں میں یعنی کتابوں اور صحیفوں میں یا لفظ و آواز سے مرکب ہوکر ہماری سینوں میں محفوظ رہیں، اس لے خدا کی کتابوں اور صحیفوں کی صداقت اور جو کچھ ان میں ہے اس کی سچائی پر ایمان لانا ضروری ہے، ورنہ رسولوں کے بعد خدا کے احکام اور ہدایتوں کے جاننے کا ذریعہ مسدود ہوجائے اور ہمارے لئے نیکی اور بدی کی تمیز کا کوئی ایسا معیار باقی نہ رہے جس پر تمام ادنیٰ و اعلیٰ، جاہل و عالم اور بادشاہ و رعایا سب متفق ہوسکیں۔
(۵) اعمال کی باز پرس اور جواب دہ کا یقین اور اس کے مطابق جزاء اور سزاء کا خیال نہ ہو تو دنیاوی قوانین کے باوجود دنیائے انسانیت سراپا درندگی اور بہیمیت بن جائے، یہی وہ عقیدہ ہے جو انسانوں کو جلوت و خلوت میں ان کی ذمہ داری محسوس کراتا ہے، ا سلئے روز جزاء اور یومِ آخرت پر ایمان رکھے بغیر انسانیت کی صلاح و فلاح ناممکن ہے اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے اس پر بے حد زور دیا ہے؛ بلکہ مکی وحی کا بیشتر حصہ اسی کی تلقین اور تبلیغ پر مشتمل ہے۔
یہی پانچ باتیں اسلام کے ایمانیات کے اصلی عناصر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر اس کے تمام رسولوں پر اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر اور روزِ جزاء پر ایمان لانا یہ عقائدِ خمسہ یکجا طور پر سورۂ بقرہ میں متعدد دفعہ کہیں مجمل اور کہیں مفصل بیان ہوئے ہیں۔
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ (البقرۃ:۱۷۷)
آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ۔ (البقرۃ:۲۸۵)
پیغمبر پر جو کچھ اتارا گیا اس پر وہ خود اور تمام مومن ایمان لائے، یہ سب لوگ خدا پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے۔
سورۂ نساء میں ان ہی عقائد کی تعلیم ہے:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ (النساء:۱۳۶)
سچا ایمان اور حسنِ عمل در حقیقت لام و ملزوم ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ ایک مومن بدکار ہوسکتا ہے یا نہیں؟ تو یہ سوال حقیقت میں خود تضاد کو مستلزم ہے، اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ کوئی مومن ہو کر بدکاری اور چوری نہیں کرسکتا، اگر کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان مسلوب ہوجاتا ہے، اور یہ بالکل واضح ہے کہ جب کوئی مومن برائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے ایمان یعنی اصول اور جذباتِ فاسدہ کے درمیان کش مکش ہوتی ہے، تھوڑی دیر یہ لڑائی قائم رہتی ہے، اگر ایمان اور اصول نے فتح پائی تو وہ اپنے کو بچالیتا ہے اور اگر جذبات غالب آتے ہیں تو ایمان اور اصول کا تخیل اس وقت دب کر اس کی نظر سے اوجھل ہوجاتا ہے اس پر بناء پر سچا مومن اور بدکردار ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے، اگر ہے تو حقیقت میں ایمان ہی کامل نہیں، یہاں بحث رسمی ایمان و مومن سے نہیں بلکہ اس ایمان سے ہے جس کے معنیٰ غیر متزلزل یقین اور ناقابلِ شک اعتقاد کے ہیں،جہاں کہیں رسمی و ظاہری ایمان کے ساتھ برائی اور بدکرداری کا وجود ہے، وہ در حقیقت ایمان کا نقص اور یقین کی کمی بھی ایمان ہی کی کمی کا نتیجہ ہے۔
لیکن بہر حال عقلی فرض اور رسمی ایمان کے لئے لحاظ سے یہ سوال ہوسکتا ہے، اور یہ مانا جاسکتا ہے کہ ایک بدکردار مومن اور نیک اخلاق کافر و مشرک میں اگر پہلا نجات کا مستحق ہے اور دوسرا نہیں ہے تو ایسا کیوں؟ اس کا جواب شرعی اور عقلی دونوں حیثیتوں سے بالکل ظاہر ہے، اسلام نے نجات کا مدار ایمان اور عمل دنوں پر رکھا ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے:
اس تفصیل سے معلوم ہوگا کہ ایک بدکردار رسمی مومن کے لئے نجات کی امید ممکن ہے، لیکن ایک حقیقی کافر و مشرک کے لئے نہیں، اور اس کی عقلی وجہ ظاہر ہے، لیکن ایک حقیقی کافر و مشرک کے درمیان وہی فرق ہے جو ایک چور اور ڈاکو کے درمیان ہے، ہر قانون دان جانتا ہے کہ ان دونوں میں قانون کی نظر میں کون مجرم زیادہ ہے، چور گو برائی کرتا ہے تاہم حکومت کا خوف اس کے دل میں ہے، مگر ڈاکو حکومت سے برسرِ پیکار ہوکر قتل و غارت کا مرتکب ہوتا ہے، اس لئے ڈاکو چور سے زیادہ سزاء کا مستحق ہے، بدکردار رسمی مومن گو گنہگار ہے مگر کبھی کبھی خوف الٰہی سے تھرّا جاتا ہے، کبھی کبھی خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے اور کبھی اپنے گناہوں پر خدا کے حضور میں شرمندہ اور نادم بھی ہوتا ہے، مگر کافر و مشرک اگر کچھ اچھے کام بھی کریں، تاہم اپنی دوسری برائیوں کے استغفار کے لئے خدا کے سامنے سرنگِوں نہیں ہوتے۔
وہ خدا نام کسی کے قائل ہی نہیں جس کے خوف سے وہ تھرّائیں، جس کی بارگاہ میں وہ گڑ گڑائیں اور جس کی محبت سرشار ہوکر وہ اس کے احکام کی تعمیل کریں، اس لئے اس مجرم کے لئے جس نے کسی مجبوری سے معذور ہوکر چھپ کر کسی قانونِ سلطنت کی نافرمانی کی رحم و بخشش کا موقع ہے، لیکن اس باغی کے لئے جو سرے سے سلطانِ وقت کو اور اس کے قانون ہی کو تسلیم نہیں کرتا رحم و بخشش کی کوئی جگہ نہیں ہے۔
لیکن یہ محض ایک تمثیل تھی، ورنہ ظاہر ہے کہ خدا کو اس کی حاجت نہیں کہ اس کے بندے اس کی حکومت کو تسلیم کریں: فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ’’بے شک خدا دنیا سے بے نیاز ہے‘‘۔
بلکہ اصل یہ ہے کہ ایک کافر و مشرک اس اصولِ کار کو تسلیم نہیں کرتا جس پر مذہبی نیکیوں کی بنیاد ہے اور ایک رسمی مومن اس اصول کو تسلیم کرتا ہے، اس کی نسبت توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ آج نہیں تو کل عمل بھی کرے گا، لیکن جو ہنوز اصول کا مخالف ہے اس کے لوٹنے کے لئے ابھی بڑی دشوار منزل باقی ہے۔
اس خالص مذہبی نقطۂ نظر سے ہٹ کر بھی اگر مومن و کافر کے باہمی فرق و امتیاز پر غور کیا جائے تو ظاہر ہوگا کہ گو بہت سے بظاہر نیک لوگوں کو جو کافر ہیں اپنے سے الگ کرنا پڑتا ہے اور بہت سے بظاہر بُرے لوگوں کو جو مومن ہیں اپنے اندر داخل کرنا پڑتا ہے، تاہم اس موقع پر اس نکتہ کو فراموش کردیا جاتا ہے کہ اس ’’اپنے‘‘ اور ’’غیر‘‘ کی وجہ تقسیم کیا ہے؟ جب اس وجہِ تقسیم کو ہم سامنے رکھیں گے تو ہم کو ناگزیر طور پر ایسا کرنا ہی پڑے گا، وجہ تقسیم خیرات کرنےوالا اور نہ خیرات کرنے والا یا جھوٹ بولنے والا اور نہ جھولنے والا نہیں ہے؛ بلکہ ایک خدا پر ایمان والا اور ایک دستور العمل (قرآن مجید) کو صحیح ماننے والا ہے، اس بناء پر اس وجہِ تقسیم کی رُو سے ایسا ہونا لازم ہے۔
یہ طریقۂ امتیاز کچھ اسلام یا مذہب ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر تحریک، ہر جماعت اور ہر اصولِ سیاست؛ بلکہ تمام انسانی تحریکات اور جماعتوں کا اصولِ تقسیم یہی ہے، ہر تحریک کا ایک صب العین اور ہر جماعت کا ایک عقیدہ (کریڈ) ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کریڈ کے مطابق پورے جوش و خروش کے ساتھ عمل کرتے ہیں، یہ اس مذہب کے مومنین صالحین ہیں، دوسرے وہ ہیں جو اس کریڈ کے مطابق عمل نہیں رکھتے، یہ اس مذہب کے غیر صالح مومنین ہیں، لیکن ایک تیسری جماعت ہے جو سرے سے اس کریڈ ہی کو تسلیم نہیں کرتی اور نہ اس کو بنیادِ عمل قرار دیتی ہے، گو اس تیسری جماعت کے بعض افراد بڑے فیاض و مخیّر ہوں یا بڑے عالم و فاضل ہوں، تاہم اس جماعت کے دائرہ کے اندر جس کا وہ کریڈ ہے ان کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے، کیا یہی وجہ نہیں کہ ایک سیاسی جماعت کے کریڈ پر یقین رکھنے والا اس کے مطابق کرنے والا اور وہ بھی جو نفس کریڈ کو تسلیم کرتا ہے، مگر اس کے مطابق عمل پیرا نہیں، اس جماعت کے پنڈال میں جگہ پاسکتا ہے، مگر وہ جو اس کریڈ ہی کو صحیح باور نہیں کرتا اس کے احاطہ میں کوئی جگہ پانے کا مستحق نہیں ہے؟ اسی پر ہر جماعت کے اصول کو قیاس کیا جاتا ہے۔
اصل یہ ہے کہ جب تک کوئی جماعت اپنے اصولِ کار، اساس جماعت اور عقیدہ کو اتنی اہمیت نہ دے گی، اس کی اہمیت جو سب اہمیتوں کو بڑھ کر ہونی چاہئے قائم نہیں رہ سکتی، اور ملت کی وہ دیوار جس کو اس قدر سخت اور مستحکم ہونا چاہئے کہ باہر کے سیلاب کا ایک قطرہ بھی اس کے اندر نہ جاسکے، اگر اس میں اصول و عقیدہ پر ایمان کا مطالبہ کئے بغیر ہر کس و ناکس کو داخلہ کی اجازت دے دی جائےتو اس مستحکم دیوار میں یقیناً رخنے پر جائیں گے اور وہ ایک لمحہ کے لئے بھی کسی سیلاب کا مقابلہ نہیں کرسکتی اور وہ جماعت ایسے پراگندہ اصول و افراد کا مجموعہ ہوگی جس کو کسی اتحاد و اشتراک اور جامعیت کا رشتہ باہم متحد و مجموع نہیں کرتا۔
مستحکم جماعتیں وہ ہیں جو اپنے کریڈ پر شدت کے ساتھ جمی رہتی ہیں اور جو اس کریڈ کو تسلیم نہیں کرتا، رکنِ جماعت نہ ہونے کی حیثیت سے وہ ان کی جماعتی برادری میں کوئی اعزاز نہیں رکھتا، کیا ایک مسلمان جبکہ کسی سیاسی جماعت کا رکن ہو تو اس کے لئے تو اصولِ کار کی یہ سخت جائز بلکہ مستحسن ہو، مگر وہی اسلامی جماعت کےممبر کی حیثیت سے اپنے اخلاقی اصول کار، اساس ملت اور مذہبی بِنائے وحدت میں یہ شدت رَوا رکھے تو کس عقل سے وہ ملات کے قابل ٹھہرایا جائے، حالانکہ ہر دلی عقیدہ کا لازمی نتیجہ اسی قسم کی شدّت اور استحکام ہونا چاہئے، پھر اگر ایک جگہ وہ ہو اور دوسری جگہ نہ ہو تو اس کے صاف معنیٰ ہیں کہ ایک کو دل کے ساتھ جو تعلق ہے وہ دوسرے کو نہیں۔
اب اگر اسلام اور اسلام کے قانون اور مذہب کو سمجھنا ہے تو اس کی اصل بنیاد پر نظر رکھنا چاہئے، جس پر اس کی پوری عمارت تعمیر ہوئی ہے، وہ بنیاد اقتصادیات کا کوئی نکتہ، دولت کا کوئی خزانہ، نسل و رنگ کا کوئی امتیاز اور ملک و وطن کی کوئی تجدید نہیں ہے بلکہ صرف ایک ہے اور وہ دنیا کی سب سے بڑی، لازوال اور وسیع و عالمگیر صداقت یعنی خدائے واحد پر ایمان ہے، یہ ہے اسلام کی ملت اور برادری کا اصل رشتہ اسی سے اس کی مذہب اور اس کے قانون کی تمام تقسیمیں اور امتیازات کی حدیث قائم ہوئی ہیں، اس کی حیثیت اسلام کی مملکت میں وہ ہے جو کل روم میں رومیت کی اور آج روس میں اصول بالشویت کی ہے۔
اس برادری کے دینی اور دنیاوی حقوق کو حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس جماعت کے فارمولے پر دستخط کرے اور اس کے کریڈ کو دل وجان سے قبول کرے، آج تمام مہذّب دنیا کسی عالمگیر برادری کی بنیاد کو تلاش کرنے میں حیران و سرگرداں ہے، مگر نہیں ملتی، حالانکہ ساڑھے تیرہ سو برس پہلے کی طرح آج بھی اسلام یہ آواز بلند کر رہا ہے کہ:
<
’’اے اہل کتاب آؤ! ہم اس ایک بات پر متفق ہوجائیں جو ہمارے اور تمہارے نزدیک یکساں ہے کہ خدائے واحد کے سواء کسی اور کی پرستش نہ کریں اور خدا کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنائیں‘‘۔
یہی توحیدِ اسلام کا وہ نظام نامہ ہے جس پر اس کے دین اور اس کی دنیا دونوں کی بنیاد ہے۔
یہ توحید یعنی عرصۂ ہستی کا صرف ایک فرمانروائے مطلق ماننا جس کے سامنے ہر جسمانی و روحانی طاقت ادب سے جھکی ہوئی ہے اور اس کی بندۂ فرمان ہے، اور ساری دنیا اسی ایک کی مخلوق و محکوم ہے اور دنیا کی ساری قومیں اس کے آگے بحیثیت مخلوق کے برابر حیثیت رکھتی ہیں، دنیا کی وہ عظیم الشان حقیقت ہے جو سر تا پا صداقت اور حق ہے، اور ایسی عالمگیر ہے جو عرصۂ وجود کے ایک ایک ذرّہ کو محیط ہے اور ایسی لا زوال ہے کہ جس کو کبھی فناء نہیں اور ایسی کھلی اور واضح کہ جس کے تسلیم کرنے میں کسی کو عذر نہیں، اور ایسی خیرِ مجسم ہے جو ہمارے اندر ہر قسم کی نیکیوں کی تحریک کرتی ہے اور جو ایسی تسکین اور تسلی ہو جو ہر مصیبت اور مشکل کے وقت ہمارے لئے صبر و استقلال کی چٹان بن جاتی ہے اور ایسا مضبوط اور مستحکم سر رشتہ جو کسی وقت ٹوٹ نہیں سکتا اور اس قدر وسیع کہ جس کے احاطۂ عام کے لئے اندر مخلوقات کی ایک ایک فرد داخل ہوکر اخلاقی حقوق و واجبات کی برادری قائم کرسکتی ہے اور خالق و مخلوق دونوں کی وابستگی اور محبت کا ذریعہ ثابت ہوسکتی ہے۔
غرض یہ ایسی عالمگیر حقیقت ہے جو سر تا پا صداقت اور حق ہے، جو کبھی نہ بدل سکی اور نہ بدلے گی، زبانوں میں جو انقلاب ہو خیالات میں جو تغیر ہو تمدّنوں میں جو اُتار چڑھاؤ ہو، قوموں میں جو تفرقے پیدا ہوں، مجازی حقیقتوں، مادی فائدوں اور سیاسی غایتوں میں جو اختلاف بھی پیدا ہو، مگر وہ ایک حقیقت ہے جو اپنی جگہ مسلم رہے گی اور جس میں کوئی تغیر اور انقلاب پیدا نہ ہوگا، کیونکہ اس کی بنیاد ایک ایسی لازوال ہستی کے یقین پر ہے جو مادّیات کی دنیا کی طرح دم بدم مٹتی اور بنتی ہے، لحظ بہ لحظہ متغیر اور منقلب نہیں۔
وہ ایک ایسی عالمگیر اور محیط ہستی کا تخیل ہے جس کے احاطۂ عام کے اندر تمام قومیں اور تمام مملکتیں بلکہ تمام مخلوقات یکساں استحقاق کے ساتھ داخل ہیں، اس کی ملکیت میں سیاہ و سپید، زنگی و رومی، ہندی و فرنگی، عربی و عجمی، امیر و غریب، عورت ومرد، شاہ پسند و جمہوریت پسند، حاکم و محکوم، آقا و غلام اور عالم و جاہل سب برابری کے ساتھ یکساں شامل ہیں، اور اس سے ایسی برادری کا رشتہ قائم ہوتا ہے جو قوموں میں میل، مملتوں میں اتحاد اور مخلوقات میں فرائض و واجبات کا احساس پیدا کرتا ہے۔
وہ خود مجسم خیر اور سر تا پا نیکی ہے، اس کی عقیدت اور محبت ہماری اندر نیکیوں کی تحریک اور برائیوں کی نفرت پیدا کرتی ہے، تاریکی میں بھی اس کی دیکھنے والی آنکھوں اور خلوتوں میں بھی اس کی جھانکنے والی نگاہوں کا سچا عقیدہ نازک سے نازک موقع پر بھی ہم کو برائیوں سے بچاتا اور نیکیوں کے لئے اُبھارتا ہے۔
جب ہمارا سہارا ٹوٹ جاتا ہے، ہر اعتماد شکست کھاجاتا ہے اور ہر امید منقطع ہوجاتی ہے اور جب افراد و قوم کے صبر و استقلال کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہییں اور ان کے وجود کی کشتی منجدھار میں پھنس جاتی ہے، اس وقت اسی ایک کی مدد کا سہارا کام آتا ہے اور اسی ایک کی نصرت کا وثوق فتح و ظفر سے ہمکنار کرتا ہے اور مایوسیوں اور ناامیدیوں کے ہر بادل کو چھانٹ کر رحمتِ الٰہی کے نور سے آنکھوں کو پُر نور اور دلوں کو مسرور کردیتا ہے۔
اب کوئی بتائے کہ کسی ایسی قوم کے لئے جو اپنے کو دائمی اور ہمیشہ کے لئے روئے زمین پر آئی ہو وار آخر الامم اور غیر منسوخ ملت ہونے کی مدعی ہو، اس کی اساسِ ملت بننے کے لئےہر روز بدل جانے والے اور ہر صدی میں منقلب ہوجانے والے تخیلات اور نظریات کبھی اساسِ ملت قرار پاسکتے ہیں، اور ایسی قوم کے لئے جوکسی نسل، کسی رنگت اور کسی قطعۂ زمین میں اپنے کو محدود نہ کرے، اس عالمگیر خدائی برادری سے بڑھ کر کوئی برادری نہیں مناسب ہوسکتی ہے۔
پھر ایسا عقیدہ جو تنہاء ہماری ملت کا اساس ہی نہ ہو بلکہ ہمارے عمل کی بنیاد ہو اس خلّاقِ عالم اور علّام الغیوب کے ایمان کے سواء کوئی دوسرا نہیں ہوسکتا، یہ لازوال اور زندۂ جاوید ہستی ہماری ملت کی لازوال اور زندۂ جاوید بناتی ہے، یہ عالمگیر اور محیط ہستی ہمارے اندر عالمگیر اخوت اور عمومی برادری کا رشتہ قائم کرتی ہے، وہ خیرِ مجسم اور سرا پا نیک ہستی ہم کو خیر کی دعوت اور نیکی کی صدا دیتی ہے، اس کے کمالی اوصاف ہم کو اپنے اخلاقی کمال کا نصب العین عطا کرتے ہیں، اس کے اسماءِ حسنیٰ اور صفاتِ کاملہ کا عقیدہ ہم کو ہر حیثیت سے حسین اور کامل بننے کا درس دیتا ہے۔
اس سے ظاہر ہوگا کہ خدا وار اس کی ذات و صفات پر اعتقاد محض نظریہ کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ اس کی حیثیت تمام تر عملی ہے، اس کی صفاتِ عالیہ ہمارے اوصافِ حسنہ کے لئے نمونہ ہیں، اور اس کے محامد کریمہ ہمارے اعمال و اخلاق کی تصحیح کے لئے تحریرِ اوراق کا مسطر ہیں۔
خیر و شر کی تمیز:
جس طرح دنیا کی دوسری چیزیں فی نفسہٖ نہ خیر ہیں اور نہ شر ہم ان کو خیر یا شر صرف ان کے موقعِ استعمال کے لحاظ سے کہتے ہیں، آگ فی نفسہٖ نہ خیر ہے نہ شر، لیکن جب کوئی ظالم اس آگ سے کسی غریب کا جھونپڑا جلاکر خاکِ سیاہ کردیتا ہے تو وہ شر ہوجاتی ہے،لیکن جب اسی آگ سے کوئی رحم دل انسان چولہا گرم کرکے کسی بھوکے لئے کھانا پکاتا ہے تو وہ خیر ہوجاتی ہے، اسی طرح نیک و بد اعمال بظاہر یکساں ہیں اور ان میں نیک و بد کی تمیز نہیں کی جاسکتی جب تک کہ اس غرض و غایت کا لحاظ نہ کیا جائے جس کے لئے وہ کام کیا جاتا ہے، ایک ڈاکو کا ایک مسافر کو قتل کردینا اور ایک حکومت کا کسی ڈاکو کو پھانس دینا یکساں اتلافِ جان کا فعل ہے؛ لیکن پھر دنیا کاگر ایک کو خیر اور ایک کو شر کہتی ہے تو وہ اس غرض و غایت کی بناء پر ہے جس کے لئے یہ دونوں قتل کئے گئے ہیں، ڈاکو جس قتل کا مرتکب ہوا ہے اس سے اس کا مقصود مسافر کے مال پر ظالمانہ قبضہ تھا اور اس راہ میں اس کے مالک کے ناحق قتل کا آخری نتیجہ راستہ کی بد امنی ور ملک کی ویرانی ہے، اور سزا دینے والی حکومت کی غرض لوگوں کی جان و مال کی حفاظت، راستہ کا امن اور ملک کو آباد کرنا ہے، اس لئے پہلا فعل شر اور دوسرا خیر ہے۔
خیر و شر کی فلسفیانہ تحقیق اور ان کی باہمی تمیز نہایت مشکل ہے، جس کو نہ ہر عامی وجاہل سمجھ سکتا ہے اور نہ اس سے متاثر ہوسکتا ہے، حالانکہ خیر و شر کے اکثر امور پر تمام دنیا متفق ہے، اس لئے مذہب نے ادنیٰ سے لے کر اعلیٰ تک کے لئے ایک آسان اصول یہ بنادیا ہے کہ وہ تمام باتیں جن کو خدائے تعالیٰ پسند کرتا ہے خیر ہے اور جن کو ناپسند کرتا ہے وہ شر ہے، اس کے اس اصول سے نہ خیر و شر کی حقیقت بدلتی ہے اور نہ ان کے نفع و ضرر کا پہلو بدلتا ہے، نہ دنیا کے فائدے اور نقصان میں کمی بیشی ہوتی ہے، ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس اصول کی تاثیر دلوں میں ایسی راسخ ہوجاتی ہے کہ جنگلی اور صحرائی سے لے کر مہذب و تعلیم یافتہ تک اس اصول کے ماتحت خیر پر عمل کرنے اور شر سے بچنے کے لئے تیار ہوجاتا ہے، چنانچہ آج دنیا میں جس قدر بھی خیر کا وجود ہے اور شر سے احتراز ہے وہ اسی پیغمبرانہ تعلیم کا نتیجہ ہے فلسفیانہ نکتہ آفرینیوں کا نہیں، ارسطو اور اسپنسر کے اصولِ اخلاق کو پڑھ کر اور سمجھ کر کتنے نیک اور خوش اخلاق پیدا ہوئے اور حضرت مسیح و حضرت علیہما الصلوٰۃ و السلام کی تعلیم و تاثیر نے کتنوں کو خوش اخلاق اور نیک کردار بنایا، اور آج دنیا میں لندن و نیویارک کے بازاروں سےلے کر افریقہ کے صحراؤں اور جنگلوں اور ہندوستان کے دیہاتوں تک میں نیکی کی اشاعت اور برائی سے پرہیز کی تعلیم انبیاء کے پیروؤں کے ذریعہ ہو رہی ہے یا فلسفیوں کے بالشویکوں کے ذریعہ انجام پارہی ہے یا نازیوں کے؟ سوشلسٹوں کے ذریعہ یا فسسٹوں کے؟ دل کا چین اخلاق کی طاقت اور عالمگیر انسانی برادری کی دولت اگر ممکن ہے تو وہ صرف اس توحید کے ذریعہ جس کی دعوت اسلام دیتا ہے اور اس ایمان کی بدولت جس کو اسلام دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، جس کی وسعت میں ساری دنیا آرام کرسکتی ہے اور جس کے سایہ میں انسانوں کے بنائے ہوئے سارے امتیازات مٹ جاتے ہیں اور جس کی بنیاد اتنی مضبوط ہے کہ آسمان و زمین کی بنیادیں اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو ہٹ جائیں مگر وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتی۔
بہ شکریہ انوارِ اسلام
Jan 26 2015
الحمد للّٰہ وکفٰی وسلام علی عبادہ الذین اصطفٰی امابعد ۔ عبد اور رب کے تعلق کو سمجھنے کے لئے سورج اور چاند کی مثال کو سمجھ لینا کافی ہے۔ ان دونوں کا باہمی تعلق عجیب ہے چاند کی روشنی اسکی اپنی ذاتی نہیں ، بلکہ سورج کی روشنی سے چاند روشن نظر آتا ہے یہی حال اللہ اور بندہ کی ذاتوں کاہے۔ دونوں ذوات الگ الگ ہیں۔ ۔ ایک معدوم ایک موجود۔ ایک ناقص ایک کامل ۔ اللہ بالذات موجود۔ ساری مخلوقات اللہ سے وجود لے رہی ہیں۔ ازل سے ابد تک ساری مخلوقات اللہ کے وجود سے موجود۔ مخلوقات باذات موجود نہیں۔ البتہ موجود نظر آتی ہیں۔ جیسے چاند اپنی ذات سے منور نہ ہو کر بھی منور نظر آتا ہے۔
ِ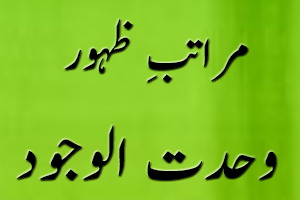
اسی حقیقت کو سمجھنے کے لئے ایک اور بعینہ مثال سینما کی ہے۔ مراتبِ ظہور کے انکشاف کے لئے بڑی واضح مثال۔
سینما میں ایک ریل ہوتا ہے۔ جس میں مختلف صورتیں بند ہوتی ہیں۔ چھوٹی، بڑی جماد و نبات، انسان وحیوان سبھی کی صورتیں، بوڑھی جوان، اندھی،گونگی، اور بہری سبھی کی شکلیں ہیں۔ اسی طرح اللہ کے علم کی ریل میں معلومات ہیں۔ ان کو معلوماتِ الٰہیہ، اعیانِ ثابتہ، اور شاکلات کہتے ہیں۔ اللہ کے علم میں مخلوقات کی جس طرح شکلیں محفوظ ہیں، اسی طرح ان شکلوں کی ذاتی قابلیات بھی محفوظ ہیں۔ ان ہی ذاتی قابلیات کو معلوماتِ الٰہیہ کے اقتضاآت یا استردات بھی کہتے ہیں۔
یہ معلومات ریل سے پردہ پر کیسے آرہے ہیں؟ ریل کے پیچھے روشنی ڈالی جارہی ہے۔ یعنی پیچھے سے ہر صورت پر نور کی تجلی ہورہی ہےتوپردہ پر صورت نظر آرہی ہے۔ نور بند ہوجائے تو ریل کی تصویر پردہ پر ہر گز ظاہر نہیں ہوتی۔ یہاں نکتہ کی بات یہ ہے کہ نہ نور صورت بنتا اور نہ صورت نور بنتی۔ نور، نور ہے، صورت ،صورت ہے۔ ہر ایک کی ذات الگ۔ نور کا کام ظاہر کرنا اور صورت کا کام ظاہر ہونا۔ نورِ الٰہی کی تجلی سے معلومات وجود پاتے چلے جارہے ہیں۔ زمین، آسمان، انسان، شیطان، جو ظاہر و موجود ہورہے ہیں وہ سب اللہ کے نور کے باعث موجود ہورہے ہیں۔ نور کے سامنے اجسام آرہے ہیں تو انکا ظہور ہورہا ہے نور کے سامنے ارواح آرہی ہیں تو ان کا ظہور ہو رہاہے۔ پھر سب اس شان سے ہورہاہے کہ اللہ میں یعنی ذاتِ الٰہی میں نہ تغیر نہ تبدل، نہ تعدد نہ تکثر۔
ریل میں صورت کی جیسی قابلیت یا استعدادِ ذاتی ہو ویسی ہی پردہ پر ظاہر ہورہی ہے۔ انسان جانور، فرشتہ، شیطان، زندہ،مردہ، اچھا، برا ،غرض جو ریل میں ہوگا وہی پردہ پر ظاہر ہوگا۔ جس طرح پردہ پر صورتوں کا ظہور ریل کی تصویروں کے مطابق ہے، اسی طرح کائنات کے پردہ پر مخلوقات کا ظہور ٹھیک معلوماتِ الٰہیہ کے مطابق ہے۔ اسی ظہور کو تخلیق کہا جاتا ہے۔
ریل کی صورت جب تک ریل میں ہے “معلوم” کہلاتی ہے۔ لیکن جب وہی ریل کی صورت پردہ پر ظاہر ہوتی ہے تو “مخلوق” کہلاتی ہے۔ ایک اور نکتہ یہ کہ ریل میں جو صورت محفوظ ہے وہ پردہ پر ظاہر ہونے کے بعد ریل سے غائب نہیں ہوجاتی بلکہ ریل میں علٰی حالہ محفوظ ہے۔ اسی طرح مخلوق ظاہر ہونے کے باوجود علمِ الٰہی میں ثابت یعنی معلوم کی معلوم۔ معلوماتِ الٰہیہ تخلیق کے بعد علم سے خارج نہیں ہوجاتے۔ اسی ایک حقیقت سے بہت سے اعتراضات حل ہوجاتے ہیں۔ ریل میں لنگڑے اور اندھےکی جوصورتیں اور قابلیتیں تھیں وہی پردہ پر ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر ریل چلانے والے سے پردے پر ظاہر ہونے والی صورت پوچھے کے مجھے لنگڑا یا اندھا کیوں بنایا؟ یہ سوال بیوقوفی کی دلیل ہے۔ حولاپن ہے۔ جواب یہ ہے کہ تو جیسا تھا ویسا ہی ظاہر کردیا گیا۔ جوں کا توں ظاہر کرنا ہی تخلیق ہے۔ جیسے کو ویسا ظاہر کرنا ہی عدل ہے۔
سرِ ظہور ایک واضح اور کھلا ہوا مسلہ ہے۔ سرِ ظہور کے حقائق و معارف کے لئے سینما کی مثال قریب ترین مثال ہے۔ جب تک روشنی پڑتی رہے گی۔ اس وقت تک ہی تصویریں نظر آتی رہینگی۔ جیسے ہی روشنی موقوف ہوجائے تصویریں ختم ہوجائیں گی۔ یہی حال اللہ تعالیٰ کی عطأ و وجود کا ہے۔ جوں ہی عطائے وجود کا سلسلہ منقطع ہوا، انسان مردہ ہے۔
اللہ لاالٰہ الاھوالحی القیوم۔ قیومیت قأیم رکھنے والی صفت کا نام ہے۔ جو ذات قأیم رکھنے والی ہے وہی ہے قیوم۔ اور وہی اللہ کی ذات۔ مشرق اور مغرب کو، انسانوں اور جانوروں کو،فرشتوں اور شیطانوں کو غرض ہشدہ ہزار عالموں کو قأیم رکھنے والی ذات قیوم۔ ایک آن کے لئے بھی قیومیت کی تجلی ہٹ جائے قصہ ہی ختم۔ ہرآن قیومیت کی تجلی کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ مسلسل روح کے قیوم، اللہ مسلسل دل کے قیوم، اللہ مسلسل جسم کے قیوم، اللہ مسلسل سب کے قیوم۔ از عرش تا فرش۔ حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت اور کلام ہر صفت کے قیوم۔
تسلسلِ قیومیت کی فہم کے لئے (ہاتھ میں کاغذ لے کر فرمایا)۔ یہ کاغذ ہاتھ میں قأیم ہے۔ اونگھ یا نیند کا غلبہ ہو تو کاغذ ہاتھ سے گرجائے۔ اگر تسبیح ہاتھ میں ہو اور اونگھ آجائے تو تسبیح گرجائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تا خذہ سنۃ ولا نوم۔ میں سب کو قأیم رکھنے والا، اگر میں اونگھ گیا تو تمہاری خیر نہیں۔ سب فنا ہوجائیں گے۔ پہچان مل گئی جس کو اونگھ نہ آئے وہی قیوم۔ ذرا سا اللہ کی توجہ ہم سے ہٹی کہ اسی کا نام موت، فنا، قیامت، یا صور۔ جدھر سے توجہ ہٹالیں ادھر فنا۔ آنِ واحد میں فنا طاری۔
خبر بھی ہے کہ کس کو قأیم رکھے ہوئے ہیں؟ محض فضل و کرم ہے کہ ماننے والوں کو اور نہ ماننے والوں کو، رحم کرنے والوں کو اور ظلم کرنے والوں کو سب کو قأیم رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے تخلیق “کن” سے ہے ویسے ہی فنا بھی “کن” سے ہے۔ قیومیت کا مسلہ اس شان اور قوت کا ہے کہ علما کی جماعت کے سامنے بلا ججھک استعمال کر لیجئے۔ مانے بغیر ،تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں۔ اور اسکا جواب نہیں۔ اسی قیومیت کا اصطلاحی نام “وحدۃالوجود” ہے۔ لیکن وحدۃالوجود کا تو حلیہ بگاڑا گیا، بدنام کیا گیا۔ اگر پوچھا جائے کہ قیومیت کیسی ہے تو علما کہینگے بہت اچھی بات ہے، ضرور بات کرنی چاہئیے۔ یہ اصطلاح سمجھنے، غور کرنے، اور پانے کی ہے۔
آخری بات یہ کہ سرکارﷺ نے بڑا پیارا اعلان فرمایا ایک اسلام کا، ایک ایمان کا، اور ایک احسان کا۔ پوچھا گیا۔ وماالاحسان؟ جواب ملا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم یکن تراہ فانہ یراک۔ (احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہاہے)۔ یعنی حاضر و موجود کا ادراک قائیم کرے اگر کسی بھائی سے یہ نہ ہو سکے تو یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رے ہیں۔ بزرگوں کی اصطلاح میں پہلا ادراک مشاہدہ کہلایا دوسرا ادراک مراقبہ۔ بلی چوہوں کو پکڑنے کیلئے مراقبہ کرتی ہے۔ یہ مثال مراقبہ کی آسانی پر دلیل ہے۔ اگر زندگی میں آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں تو کل زندگی احسانی ہوجائے۔ ایک شیخ صاحب ایک نوجوان مرید کو زیادہ چاہتے تھے۔ دوسرے مریدوں نے وجہ پوچھی تو شیخ صاحب نے ہر ایک کے ہاتھ میں چاقو اور کبوتر دیکر فرمایاکہ، ایسی جگہ ذبح کریں جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو تعمیلِ حکم میں بعضوں نے غاروں اور ویرانوں میں ذبح کیا، بعضوں نے بیت الخلأ اور بعضوں نے گھر کے پچھلے حصہ میں کاٹا۔ نوجوان نے ذبح کئے بغیر چھری اور کبوتر شیخ کو واپس کئے۔ شیخ نے وجہ پوچھی تو کہا کہ ہر جگہ اللہ موجود ہے اس لئے کہیں ذبح نہ کر سکا۔ اللہ کے دیکھتے رہنے کا حال طاری کرنے کے بعد گناۃ مشکل ہوجأیگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔
Jan 23 2015
Hazrath Maulana Shah Mufti Mohammed Nawal ur Rahman Sahab Damat Barkatuhum

Jan 21 2015
Jan 16 2015
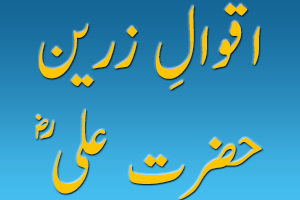
(۳) خلق خدا کے ساتھ نیکی کرنے سے جس قدر شکر گذاری ہوتی ہے وہ اور کسی صورت ممکن نہیں۔
(۴) جب مومن کا خلق اچھا ہو تو کلام لطیف ہوجاتا ہے۔
(۵) جب کسی کے احسان کا بدلہ اتارنے سے تمہارے ہاتھ قاصر رہیں تو زبان سے ضرور اس کا شکریہ ادا کرو۔
(۶) جو حقوق تمہارے نفس کے ذمہ ہیں ان کے ادا کرنے کا تم خود سے تقاضا کرو، تاکہ تم اواروں کے تقاضے سے محفوظ رہو۔
(۷) انسان کے چہرے کا حسن اللہ تعالیٰ کی عمدہ عنایت ہے۔
(۸) کارخانۂ قدرت میں فکر کرنا بھی عبادت ہے۔
(۹) دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔
(۱۰) عقلمند آدمی ہمیشہ فکر اور غم میں مبتلا رہتا ہے۔
(۱۱) برائیوں سے پرہیز کرنا نیکیاں کمانے سے بہتر ہے۔
(۱۲) اگرچہ کوئی قدر شناس نہ ملے مگر تم اپنی نیکی بند نہ کرو۔
(۱۳) عقیدہ میں شک رکھنا شرک کے برابر ہے۔
(۱۴) صدق دل کے ساتھ سو رہنا اس نماز سے کہیں اچھا ہے جو شک کے ساتھ ادا کی جائے۔
(۱۵) جب تک آدمی کا حال پوری طرح معلوم نہ ہو اس کی نسبت بزرگی کا اعتقاد نہ رکھو۔
(۱۶) قابلِ صحبت بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔
(۱۷) بدکاروں کی صحبت سے بچو کیونکہ برائی برائی سے جلد مل جاتی ہے۔
(۱۸) بے موقع حیاء بھی باعثِ محرومی ہے۔
(۱۹) گناہوں سے نادم ہونا بھی گناہوں سے معافی مانگنے جیسا ہے۔
(۲۰) گناہوں پر نادم ہونا ان کو مٹادیتا ہے اور نیکیوں پر غرور کرنا نیکیوں کو برباد کردیتا ہے۔
(۲۱) برا کام لوگوں کے سامنے کرنا مناسب نہیں بلکہ اُسے چھپ کر بھی نہ کرو۔
(۲۲) مشورہ باعث تقویت ہے۔
(۲۳) شکر نعمت کا باعث اور ناشکری حصولِ زحمت کا باعث ہے۔
(۲۴) کسی دوسرے کے گرنے سے خوش مت ہونا، تمہیں کیا معلوم کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟
(۲۵) ادب بہترین کمالات اور خیرات افضل ترین عبادات میں سے ہے۔
(۲۶) سخاوت کے ساتھ احسان رکھنا نہایت کمینگی ہے۔
(۲۷) بہترین بخشش وہ ہے جو سوال سے پہلے کی جائے۔
(۲۸) مال فتنوں کا سبب، حوادت کا ذریعہ، تکلیف کا باعث اور رنج و مصیبت کی سواری ہے۔
(۲۹) بےشک لوگ سونے چاندی کی نسبت اچھے ادب کے زیادہ بخیل ہو وہ اپنی عزت کے دینے میں اسی قدر سخی ہوتا ہے۔
(۳۰) دولتمندی کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو، یہ ایسی لمبی مستی ہے کہ اس ےس بہت دیر میں ہوش آتا ہے۔
(۳۱) جو شخص مال دینے میں زیادہ بخیل ہو وہ اپنی عزت کے دینے میں اسی قدر سخی ہوتا ہے۔
(۳۲) دولت، حکومت اور مصیبت میں انسان کی عقل کا امتحان ہوتا ہے۔
(۳۳) کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے لئے مصیبت ہے۔
(۳۴) تنگ دستی جسے لوگ معیوب سمجھیں اس مالداری سے اچھی ہے جس سے انسان گناہوں اور خرابی میں مبتلا ہوکر ذلیل و خوار ہو۔
(۳۵) تنگ دست آدمی جو رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھے اس مالدار سے اچھا ہے جو ان سے قطع تعلق رکھے۔
(۳۶) تنگ دستی میں سخاوت کی کوئی صورت نہیں اور کھانے کی حرص کے ساتھ اچھی صحت کی کوئی دلیل نہیں۔
(۳۷) حرص سے روزی بڑھ نہیں جاتی، مگر آدمی کی قدر گھٹ جاتی ہے۔
(۳۸) تواضع علم کا ثمر ہے۔
(۳۹) لوگوں کے پاس عاجزی کرنے سے ان سے نا امید ہونا اچھا ہے ۔
(۴۰) آدمی اگر عاجز ہو اور نیک کام کرتا رہے تو اس سے اچھا ہے کہ قوت رکھے اور بُرے کام نہ چھوٹے۔
(۴۱) ظلم نعمتیں دور کرتاہے اور سرکشی موجب عذابِ الٰہی ہے۔
(۴۲) بے قراری کچھ تقدیر ِ الٰہی کو نہی مٹاتی مگر اجر اور ثواب کو ضرور ضائع کردیتی ہے۔
(۴۳) غضب سے بچو کہ اس کا شروع جنون اور آخر ندامت ہے۔
(۴۴) تمام لوگوں میں نیک کام پر سب سے زیادہ قادر وہ شخص ہے جس کو جلد غصہ نہ آئے۔
(۴۵) دنیا ایک ایسا گھر ہے جس کا اول تکلیف اور اس کا آخر فناء ہے۔
(۴۶) دنیا اگر آنے لگے تو آتی رہتی ہے اور اگر پیٹھ پھیر لے تو چلی ہی جاتی ہے۔
(۴۷) دنیا ایسی مصیبتوں اور اموات کا مجموعہ ہے جو سخت تکلیف دہ اور غیر مختتم ہیں۔
(۴۸) دین کی دوستی دنیا کا نقصان کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔
(۴۹) خدا کی رحمت سے نا امید ہونا نہایت نقصاندہ ہے۔
(۵۰) انسان کی سب آرزوئیں کبھی پوری ہونے والی نہیں۔
(۵۱) لمبی آرزو اور خلوصِ عمل کبھی جمع نہیں ہوسکتے۔
(۵۲) فضول امیدوں پر بھروسہ کرنے سے بچو، کہ یہ احمقوں کا سرمایہ ہے۔
(۵۳) سب سے بڑی مصیبت امید کا منقطع کردینا ہے۔
(۵۴) جو شخص بہت بڑی بڑی امیدیں باندھتا ہے وہ موت کو بہت کم یاد کرتا ہے۔
(۵۵) جب تم امیدیں باندھتے باندھتے دور جا پہنچو تو موت کی ناگہانی آمد کو یاد کرو۔
(۵۶) کسی چیز سے اچھی طرح ناامید ہوجانا اس کی طلب میں ذلت اٹھانے سے بہتر ہے۔
(۵۷) موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔
(۵۸) مال امیدوں کو مضبوط کرتا ہے اور موت آرزوؤں کی جڑ کاٹتی ہے۔
(۵۹) تکلیف اور تنگی آرام سے موت و حیات سے نہایت قریب ہے۔
(۶۰) موت سے بڑھ کر کوئی چیز سچی نہیں اور امید سے بڑھ کر کوئی چیز جھوٹی نہیں۔
(۶۱) زمانے کے پل پل کے اندر آفات پوشیدہ ہیں۔
(۶۲) دنیا مسافر خانہ ہے، مگر بدبختوں نے اُسے اپنا وطن بنا رکھا ہے۔
(۶۳) عادت پر غالب آنا کمالِ فضیلت ہے۔
(۶۴) خواہش پرستی ہلاک کرنے والا ساتھی ہے اور بری عادت ایک مور آور دشمن ہے۔
(۶۵) خواہش کی تابعداری ایک لا علاج مرض ہے۔
(۶۶) عقلمند آدمی اپنے آپ کو پست کرکے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔
(۶۷) عقلمند وہ ہے جو غیروں سے عبرت حاصل کرے نہ کہ خود باعث عبرت بن جائے۔
(۶۸) ہوشیار وہ ہے جو زمانہ کی روشنی پر چلے۔
(۶۹) عقلمندی کا ایک نصف بردباری اور دوسرا نصف چشم پوشی ہے۔
(۷۰) کمینے کے ساتھ بھلا کرنا نہایت بُرا فعل ہے۔
(۷۱) فاسق کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں۔
(۷۲) بُرا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھتا، کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے۔
(۷۳) فسق و فجور کے مقامات سے دور رہو، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مقام اور اس کے عذاب کے محلات ہیں۔
(۷۴) فرصت کو کھونا بڑی مصیبت ہے۔
(۷۵) علم مالدار کی زینت اور تنگدستوں کے لئے فراخی کا ذریعہ ہے۔
(۷۶) علم بے عمل ایک آزار اور عمل بغیر اخلاص بیکار ہے۔
(۷۷) علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تم مال کی۔
(۷۸) علم کی خوبی اس پر عمل کرنے اور احسان کی خوبی اس کے جتلانے پر منحصر ہے۔
(۷۹) جس بات کا عالم نہ ہو اُسے بُرا مت سمجھو، ہوسکتا ہے کہ کئی باتیں ابھی تک کان تک نہ پہنچی ہوں۔
(۸۰) خود ستائی کے برابر کوئی حماقت اور علم سے زیادہ کوئی رہنما نہیں۔
(۸۱) تھوڑا علم فساد علم کا موجب ہے اور صحت عمل اور صحتِ علم پر منحصر ہے۔
(۸۲) علم کے بیان کرنے والے بہت ہیں، لیکن بہت کم عمل کرنے والے ہیں۔
(۸۳) اپنی لاعلمی کے اظہار کو کبھی بُرا نہ سمجھو۔
(۸۴) دوستی ایک خود پیدا کردہ رشتہ ہے۔
(۸۵) دشمن ایک بھی بہت ہے اور دوست زیادہ بھی تھوڑے ہیں۔
(۸۶) دنیاداروں کی دوستی ایک ادنیٰ بات سے دور ہوجاتی ہے۔
(۸۷) اگر کوئی قابل شخص دوستی کے لائق نہ ملے تو کسی نااہل سے دوستی مت کرو۔
(۸۸) دوست سے دھوکہ کھانے اور دشمن سے مغلوب ہونے سے بچو۔
(۸۹) انسان جو حالت اپنے لئے پسند کرے اُسی حالت میں رہتا ہے۔
(۹۰) تجربہ سے پہلے کسی پر اطمینان کرنا عقلمندی کے خلاف ہے۔
(۹۱) تجربے کبھی ختم نہیں ہوتے، عقل مند وہ ہے جو ان میں ترقی کرتا ہے۔
(۹۲) بات کی جانچ کرو اور کہنے والے کی طرف خیال نہ کرو کہ کون ہے۔
(۹۳) جب تک کسی آدمی سے بات چیت نہ ہو اس کو حقیر نہ سمجھو۔
(۹۴) حق نہایت زبردست مددگار اور جھوٹ بہت ہی کمزور معاون ہے۔
(۹۵) سچائی میں اگرچہ خوف ہو مگر باعثِ نجات ہے اور جھوٹ میں گو اطمینان ہو مگر موجبِ ہلاکت ہے۔
(۹۶) سچا آدمی سچائی کی بدولت اس مرتبہ کو پہنچ جاتا ہے جسے جھوٹا اپنے مکر و فریب سے نہیں پاسکتا۔
(۹۷) جیسے جہالت کی بات کہنے میں کوئی خوبی نہیں، ایسا ہی حق سے چپ رہنے میں کوئی بھلائی نہیں۔
(۹۸) صبر ایک ایسی سواری ہے جو کبھی ٹھوکر نہیں کھاتی۔
(۹۹) صبر کی بہ نسبت بے قراری زیادہ تکلیف دہ ہے۔
(۱۰۰) مصائب کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔
(اقوال کا خزانہ)
۱۔ ہرانسان کی قیمت اس کام سے لگائی جاتی ہے جس کو وہ(دوسروں کے مقابلہ میں اوراپنے دوسرے کاموں کے مقابلہ میں)بہتر طریقہ پر انجام دیتا ہے ۔(انسان کی قیمت اس کے خاص ہنر سے لگائی جاتی ہے)
۲۔لوگوں سے ان کی ذہنی سطح اورفہم کے مطابق بات کرو کیا تمہیں پسند ہے کہ کوئی (اپنے فہم اورادراک سے بالا ہونے کی وجہ سے)اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلائے۔
۳۔ایک شریف آدمی اس وقت بے قابو ہوتا ہے،جب بھوکا ہو اورایک پست فطرت انسان اس وقت بے قابو اورجامہ سے باہر ہوتا ہے،جب شکم سیر ہو(اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو)
۴۔ان دلوں کو بھی آرام دو،ان کے لئے حکمت آمیزلطیفے تلاش کرو،کیونکہ جسموں کی طرح دل بھی تھکتے اوراکتاجایا کرتے ہیں۔
۵۔نفس خواہشات کو ترجیح دیتا ہے،سہل اورسست راہ اختیار کرتا ہے،تفریحات کی طرف لپکتا ہے،برائیوں پر ابھارتا ہے،بدی اس کے اندر جاگزیں رہتی ہے،راحت پسند ہے،کام چور ہے،اگر اس کو مجبور کروگے،تولاغر ہوجائے گا اوراگر چھوڑوگےتوہلاک ہوجائے گا۔
۶۔خبردار ہوشیار! اللہ کے سوا قطعاً تم میں سے کوئی کسی سے امید نہ قائم کرے،اپنے گناہوں کے سوا کسی بات سے نہ ڈرے،اگر کوئی چیز نہ آتی ہو تو سیکھنے سے شرم نہ محسوس کرے،اوراگر اس سے کوئی ایسی بات دریافت کی جائے جس کونہیں جانتا ہو تو کہہ دے مجھے معلوم نہیں۔
۷۔غربت ذہانت کو کند کردیتی ہے،ایک غریب آدمی اپنے وطن میں رہ کر بھی پردیسی ہوتاہے۔
۸۔ناکارگی آفت ہے،صبر بہادری ہے،زہد خزانہ ہے،خوف ِخدا ڈھال ہے۔
۹۔اخلاق وآداب ایسے جوڑے ہیں جو بار بار نئے نئے پہنے جاتے ہیں،ذہن ایک صاف و شفاف آئینہ ہے۔
۱۰۔جب کسی کااقبال ہوتا ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اس سے منسوب کردی جاتی ہیں اورجب زوال آتا ہے تو اس سے اُس کی ذاتی خوبیوں کا بھی انکار کردیا جاتا ہے۔
۱۱۔جب کوئی بات آدمی دل میں پوشیدہ رکھتا ہے تو زبان سے اس کے اشارے مل جاتے ہیں،چہرہ کے اتار چڑھاؤ سے معلوم ہوتا ہے۔
۱۲۔کسی دوسرے کے غلام مت بنو،جب کہ اللہ تعالی نے تم کو آزاد پیدا کیا ہے۔
۱۳۔جھوٹی تمناؤں پر بھروسہ کرنے سے بچتے رہو، تمنائیں بیوقوفوں کا سرمایہ ہیں۔
۱۴۔تم کو بتاؤں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟وہ جو بندگانِ خدا کو معصیت کی باتیں حسین بناکر نہ دکھائے اورخدا کی کاروائی سے بے خطر نہ رکھے اور اس کی رحمت سے مایوس بھی نہ کرے۔
۱۵۔لوگ محوخواب ہیں جب مریں گے تو ہوش آجائے گا۔
۱۶۔لوگ جن باتوں کو نہیں جانتے ان کے دشمن ہوجاتے ہیں۔
۱۷۔لوگ اپنے آباء واجداد سے زیادہ اپنے زمانہ کے مشابہ ہوتے ہیں (یعنی لوگوں پر وقت اورماحول کا اثر زیادہ پڑتا ہے)
۱۸۔انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے (یعنی جب تک آدمی بولے نہیں اس کی علمیت اورحقیقت پوشیدہ رہتی ہے)
۱۹۔جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس کے لئے کوئی بڑا خطرہ یادھوکہ کا اندیشہ نہیں۔
۲۰۔کبھی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔
(المرتضیٰ از مولانا ابوالحسن علی ندوی:۲۸۶،۲۹۱)
۲۱۔آپ اپنے یقین کو شک نہ بنائیں (یعنی روزی کا ملنا یقینی ہے اس کی تلاش میں اس طرح اور اتنا نہ لگیں کہ گویا آپ کو اس میں کچھ شک ہے)اوراپنے علم کو جہالت نہ بنائیں (جو علم پر عمل نہیں کرتا وہ اورجاہل دونوں برابر ہوتے ہیں)اوراپنے گمان کوحق نہ سمجھیں (یعنی آپ اپنی رائے کو وحی کی طرح حق نہ سمجھیں)اوریہ بات آپ جان لیں کہ آپ کی دنیا تو صرف اتنی ہے جو آپ کو ملی اورآپ نے اسے آگے چلا دیا یا تقسیم کرکے برابر کردیا پہن کر پرانا کردیا۔
(کنز العمال:۸/۲۲۱)
۲۲۔خیریہ نہیں ہے کہ تمہارا مال اورتمہاری اولاد زیادہ ہوجائے ؛بلکہ خیر یہ ہے کہ تمہارا علم زیادہ ہو اورتمہاری بردباری کی صفت بڑی ہو اوراپنے رب کی عبادت میں تم لوگوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔
۲۳۔اگر تم سے نیکی کا کام ہوجائے تو اللہ تعالی کی تعریف کرو اوراگر برائی کا کام ہوجائے تو اللہ تعالی سے استغفار کرو۔
۲۴۔دنیا میں صرف دو آدمیوں کے لئے خیر ہے ایک تو وہ آدمی جس سے کوئی گناہ ہوگیا اورپھر اس نے توبہ کرکے اس کی تلافی کرلی دوسرا وہ آدمی جو نیک کاموں میں جلدی کرتا ہو۔
۲۵۔جو عمل تقویٰ کےساتھ ہو وہ کم شمار نہیں ہوسکتا؛ کیونکہ جو عمل اللہ کے ہاں قبول ہو وہ کیسے کم شمار ہوسکتا ہے۔(کیونکہ قرآن میں ہے کہ اللہ متقیوں کے عمل کو قبول فرماتے ہیں)
(مذکورہ اقوال کے لئے دیکھئے،حلیۃ الاولیاء:۱/۷۵)
۲۶۔سب سے بڑی مالداری عقلمندی ہے ؛یعنی مال سے بھی زیادہ کام آنے والی چیز عقل اور سمجھ ہے اورسب سے بڑی فقیری حماقت اوربے وقوفی ہے،سب سے زیادہ وحشت کی چیز اورسب سے بڑی تنہائی عجب اورخود پسندی ہے اورسب سے زیادہ بڑائی اچھے اخلاق ہیں۔
۲۷۔بے وقوف کی دوستی سے بچنا؛ کیونکہ وہ فائدہ پہنچاتے پہنچاتے تمہارا نقصان کردے گا اورجھوٹے کی دوستی سے بچنا ؛کیونکہ جو تم سے دور ہے یعنی تمہارا دشمن ہے اسے تمہارے قریب کردے گا اور جو تمہارے قریب ہے یعنی تمہارا دوست ہے اسے تم سے دور کردے گا(یا وہ دور والی چیز کو نزدیک اورنزدیک والی چیز کو دور بتائے گا اورتمہارا نقصان کردے گا)اورکنجوس کی دوستی سے بھی بچنا ؛کیونکہ جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی وہ اس وقت تم سے دور ہوجائے گا اوربد کار کی دوستی سے بچنا ؛کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا۔
(حیاۃ الصحابۃ:۳/۵۴۹)
۲۸۔توفیق خداوندی سب سے بہترین قائد ہے اور اچھے اخلاق بہترین ساتھی ہیں،عقلمندی بہترین مصاحب ہے ،حسن ادب بہترین میراث ہے اور عجب وخود پسندی سے زیادہ سخت تنہائی اوروحشت والی کوئی چیز نہیں۔
حیاۃ الصحابۃ:۳/۵۴۹)
۲۹۔اسے مت دیکھو کہ کون بات کررہا ہے ؛بلکہ یہ دیکھو کہ کیا بات کہہ رہا ہے۔
۳۰۔ہربھائی چارہ ختم ہوجاتا ہے صرف وہی بھائی چارہ باقی رہتا ہے جو لالچ کے بغیر ہو۔
۳۱۔اللہ کی قسم! اہل حق کا اکٹھا ہونا ہی اصل میں اکٹھا ہونا ہے چاہے وہ تعداد میں کم ہوں اوراہل باطل کا اکٹھا ہونا حقیقت میں بکھر جانا ہے چاہے وہ مقدار میں زیادہ ہوں۔
(حیاۃ الصحابۃ:۲/۲۰،کنزالعمال:۱/۶۹)
۳۲۔بیشک مومن تو ایسے لوگ ہیں کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اگرچہ ان کے وطن اورجسم دور ہوں اورمنافقین ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں۔
(کنز العمال:۳/۱۴۱)
۳۳۔ میں کسی مسلمان کی ایک ضرورت پوری کردوں یہ مجھے زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔
(کنزالعمال:۳/۳۱۷)
۳۴۔تواضع کی بنیاد تین چیزیں ہیں،آدمی کو جو بھی ملے اسے سلام میں پہل کرے اورمجلس کی اچھی جگہ کے بجائے ادنی جگہ میں بیٹھنے پر راضی ہوجائے اور دکھاوے اورشہرت کو بُرا سمجھے۔
(کنزالعمال:۲/۱۴۳)
۳۵۔جو آدمی بھی اللہ تعالی پر بھروسہ کرے اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالی جو حالت بھی اس کے لئے پسند فرماتے ہیں وہ خیر ہی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی حالت کے علاوہ کسی اور حالت کی کبھی تمنا نہ کرے گا اور یہ کیفیت رضا بر قضا کے مقام کا آخری درجہ ہے۔
(کنزالعمال:۲/۱۴۵)
۳۶۔جو اللہ کے فیصلہ پر راضی ہوگا تو اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تو ہوکر رہے گا ؛لیکن اسے (اس پر راضی ہونے کی وجہ سے)اجر ملے گا اورجو اس پر راضی نہ ہوگا تو بھی اللہ کا فیصلہ ہوکر رہے گا؛ لیکن اس کے نیک عمل ضائع ہوجائیں گے۔
(کنز العمال:۲/۱۴۵)
۳۷۔جہاد کی تین قسمیں ہیں ایک ہاتھ سے جہاد کرنا دوسرا زبان سے جہاد کرناتیسرا دل سے جہاد کرنا،سب سے پہلے ہاتھ والا جہاد ختم ہوگا، پھر زبان والا ختم ہوگا پھر دل والا،جب دل کی یہ کیفیت ہوجائے کہ وہ نیکی کو نیکی نہ سمجھے اوربرائی کو برائی نہ سمجھے تو اسے اوندھا کردیا جاتا ہے یعنی اس کے اوپر والے حصے کو نیچے کردیا جاتا ہے۔ (پھر خیر اورنیکی کا جذبہ اس میں نہیں رہتا )
(حیاۃ الصحابۃ:۲/۸۱۲)
۳۸۔زبان سارے بدن کی اصلاح کی بنیاد ہے، جب زبان ٹھیک ہوجائے تو سارے اعضاء ٹھیک ہوجاتے ہیں اورجب زبان بے قابو ہوجاتی ہے تو تمام اعضاء بے قابوہوجاتے ہیں۔
(حیاۃ الصحابۃ:۲/۷۹۷)
۳۹۔اپنا بھید اپنے تک محفوظ رکھو اورکسی پر ظاہر نہ کرو؛ کیونکہ ہر خیرخواہ کے لئے کوئی نہ کوئی خیر خواہ ہوتا ہے۔
(حیاۃ الصحابۃ:۲/۷۹۷ٌ)
۴۰۔میں نے گمراہ انسانوں کو دیکھا ہے کہ وہ کسی آدمی کو بے داغ صحیح نہیں رہنے دیتے۔
(حیاۃ الصحابۃ:۲/۷۹۷)
۴۱۔جیسے تم خوف کے وقت عمل کرتے ہو ایسے ہی دوسرے اوقات میں بھی شوق اوررغبت سے عمل کیاکرو۔
۴۲۔میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جو جنت جیسی ہو اور پھر بھی اس کا طالب سویا ہوا ہو اورنہ ہی ایسی کوئی چیز دیکھی جو جہنم جیسی ہو اورپھر بھی اس سے بھاگنے والا سوتا رہے۔
۴۳۔غورسے سنو!جو حق سے نفع نہیں اٹھاتا اسے باطل ضرور نقصان پہنچاتا ہے۔
۴۴۔جسے ہدایت سیدھے راستے پر نہ چلاسکی،اسے گمراہی سیدھے راستہ سے ضرور ہٹا دے گی۔
(مذکورہ اقوال کے لئے دیکھئے: البدایۃ والنھایۃ:۷۱۸)
۴۵۔جو جان بوجھ کر محتاج بنتا ہے وہ محتاج ہوہی جاتا ہے۔
۴۶۔جو بلا اورآزمائش کے لئے تیاری نہیں کرتا جب اس پر آزمائش آتی ہے تو وہ صبر نہیں کرسکتا۔
۴۷۔جو کسی سے مشورہ نہیں کرتا اسے ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔
۴۸۔آدمی کو سیکھنے میں حیا نہیں کرنی چاہیے اورجس آدمی سے ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ نہیں جانتا تو اسے یہ کہنے میں حیا نہیں کرنی چاہے کہ میں نہیں جانتا۔
(مذکورہ اقوال کے لئے دیکھئے: کنزالعمال:۸/۲۱۸)
۴۹۔علم مال سے بہتر ہے،علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اورمال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے،علم عمل کرنے سے بڑھتا ہےاور مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے ،عالم کی محبت دین ہے جس کا اللہ کے ہاں سے بدلہ ملے گا،علم کی وجہ سے عالم کی زندگی میں اس کی بات مانی جاتی ہے اوراس کے مرنے کے بعد اس کا اچھائی سے تذکرہ کیا جاتا ہے۔
(حیاۃ الصحابۃ:۳/۱۸۰،۱۸۱)
۵۰۔حقیقی عالم وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کرے اورنہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی انہیں کھلی چھٹی دے اور نہ انہیں اللہ کی پکڑسے بے خوف اوربے فکر ہونے دے اور نہ قرآن کے علاوہ کسی اورچیز میں ایسا لگے کہ قرآن چھوٹ جائے۔
(حیاۃ الصحابۃ:۳/۲۳۷)
۵۱۔اس عبادت میں خیر نہیں ہے جس میں دینی علم نہ ہو اور اس دینی علم میں خیر نہیں ہے جسے آدمی سمجھا نہ ہو یا جس کے ساتھ پرہیزگاری نہ ہو اورقرآن کی اس تلاوت میں کوئی خیر نہیں جس میں انسان قرآن کے معنی اورمطلب میں غوروفکر نہ کرے۔
(حیاۃ الصحابۃ:۳/۲۳۷)
۵۲۔حضرت علیؓ نے استاد کے آداب کو ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا:
۱۔تمہارے استاد کا یہ حق ہےکہ تم اس سے سوال زیادہ نہ کرو اوراسے جواب دینے کی مشقت میں نہ ڈالو یعنی اسے مجبور نہ کرو۔
۲۔جب وہ تم سے منہ دوسری طرف پھیرلے تو پھر اس پر اصرار نہ کرو اور جب وہ تھک جائے تو اس کے کپڑے نہ پکڑو اورنہ ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کرو اورنہ آنکھوں سے۔
۳۔اس کی لغزشیں تلاش نہ کرو اوراگر اس سے کوئی لغزش ہوجائے تو تم اس کے لغزش سے رجوع کا انتظار کرو اور جب وہ رجوع کرلے تو تم اسے قبول کرلو۔
۴۔اپنے استاد سے یہ نہ کہو کہ فلاں نے آپ کی بات کے خلاف بات کہی ہے۔
۵۔اس کے کسی راز کا افشاء نہ کرو۔
۶۔اس کے پاس کسی کی غیبت نہ کرو اس کے سامنے اوراس کے پیٹھ پیچھے دونوں حالتوں میں اس کے حق کا خیال کرو۔
۷۔تمام لوگوں کو سلام کرو ؛لیکن استادکو خاص طور پرسلام کرو۔
۸۔اس کے سامنے بیٹھو اگر اسے کوئی ضرورت ہوتو دوسروں سے آگے بڑھ کر اس کی خدمت کرو۔
۹۔اس کے پاس جتنا وقت بھی تمہارا گزرجائے تنگدل نہ ہونا ؛کیونکہ یہ عالم کھجور کے درخت کی طرح ہے جس سے ہر وقت کسی نہ کسی فائدے کے حصول کا انتظار رہتا ہے،یہ عالم اس روزہ دار کے درجہ میں ہے جو اللہ کے راستہ میں جہاد کررہا ہو جب ایسا عالم مرجاتا ہے تو اسلام میں ایسا شگاف پڑجاتا ہے جو قیامت تک پر نہیں ہوسکتا۔
(حیاۃ الصحابۃ:۳/۲۳۸)
۵۳۔((الأیام صحائف اعمار کم فخلدوھاصالح اعمالک))
‘‘یہ ایام تمہاری عمروں کے صحیفے ہیں،اچھے اعمال سے ان کو دوام بخشو’’
(متاع وقت اورکاروان علم :۵۵)
۵۴۔حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضورﷺ کے بعد مجھے جتنا فائدہ حضرت علیؓ کے اس خط سے ہوا اتنا فائدہ اورکسی چیز سے نہیں ہوا،آپ نے میری طرف خط میں لکھا تھا:
‘‘اما بعد!یہ بات شک وشبہ سے بالاتر ہے کہ آدمی کو اس چیز کے حاصل کرنے سے خوشی ہوتی ہے جو کبھی اس سے ضائع نہ ہو اورآدمی اس چیز کے ضائع ہونے پر غمگین اورنادم ہوتا ہے،جس کا حاصل کرنا اس کے لئے ممکن نہیں،پس آپ کی خوشی ہمیشہ آخرت کی چیزوں کے حصول اورآپ کا غم آخرت کی چیزوں سے محرومی سے وابستہ ہونا چاہیے،دنیا کی کوئی چیز ضائع ہوجائے تو افسوس مت کرنا اوراگر دنیا کی کوئی چیز مل جائے تو خوشی کی وجہ سے تکبراورخود پسندی کا شکار مت ہونا،تمہارے زیر نظر آخرت کی زندگی ہی ہونی چاہئے’’
(نفحۃ العرب:۱۳۱)
۵۵۔کچھ لوگ اللہ کی عبادت جنت کی رغبت اورلالچ کی وجہ سے کرتے ہیں ‘ فتلک عبادۃ التجار’ یہ تاجروں والی عبادت ہے،کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خوف اورڈر کی وجہ سے اللہ کی عبادت میں مصروف نظر آتے ہیں ‘فتلک عبادۃ العبید’ یہ غلاموں والی عبادت ہے اور اللہ کی مخلوق میں کچھ ایسے بلند ہمت لوگ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت جنت کی لالچ اورجہنم کے خوف سے بے نیاز ہوکر صرف اورصرف اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے کرتے ہیں‘فتلک عبادۃ الاحرار’ یہ آزاد اور بلند حوصلہ لوگوں کی عبادت ہے۔
(مرقاۃ المفاتیح:۳/۱۴۲)
۵۶۔جس شخص کی زبان اس پر حاکم بن جائے وہ ذلیل ہوکر رہتا ہے۔
۵۷۔عقل مند کا سینہ اس کے رازوں کا صندوق ہوتا ہے۔
(نھج البلاغۃ،الجزء الرابع:۵۳۹)
۵۸۔انسان پر تعجب کرو جو چکنائی سے بنی ہوئی چیز(آنکھ)سے دیکھتا ہے،گوشت (زبان)سے بولتا ہے،ہڈی (کان)سے سنتا ہے اور ایک خالی جگہ(ناک)سے سونگھتا ہے۔
۵۹۔جب دنیا کسی کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے مل جاتی ہیں اورجب کسی سے رخ پھیرتی ہے تو اس کی خوبیوں سے بھی اسے محروم کردیتی ہے۔
۶۰۔لوگوں کے ساتھ ایسا طرز زندگی اختیار کرو کہ تمہارے مرنے پر وہ آبدیدہ ہوجائیں اورتمہاری زندگی میں وہ تمہارے ہم نشین رہیں۔
۶۱۔سب سے کمزورآدمی وہ ہے جو لوگوں کو دوست نہ بناسکے اوراس سے بھی کمزور وہ شخص ہے جو لوگوں کو دوست بنانے کے بعد ضائع کردے۔
۶۲۔جس کے قریبی لوگ اس کی قدر نہیں کرتے تو دور والے اس کی توقیر وتعظیم میں لگ جاتے ہیں۔
(نھج البلاغۃ،الجزء الرابع:۵۴۰)
۶۳۔ہیبت وخوف سے ناکامی اورحد سے زیادہ حیاء کرنے سے محرومی ملتی ہے۔
۶۴۔مواقع بادلوں کی طرح آتے جاتے رہتے ہیں پس اگر کسی خیر کا موقع مل جائے تو اسے ضائع مت کرو۔
۶۵۔اے ابن آدم !تو دیکھ رہا ہے کہ تیرا رب تجھ پر ہر آن ہر گھڑی نعمتیں برسارہا ہے ؛جبکہ تو اس کی معصیت پر ڈٹا ہوا ہے،ان نعمتوں کو دیکھ کر تجھے گناہوں سے باز آجانا چاہیئے۔
۶۶۔جب کوئی کسی بات کو چھپاتا ہے تو وہ اس کی زبان کی لغزشوں اورچہرے کے خدوخال سے ظاہر ہوجاتی ہے۔
۶۷۔جب تک بیماری کے ساتھ کام کرنا ممکن ہو کرتے رہو۔
۶۸۔سب سے افضل زہد،زہدکوچھپانا ہے۔
(نھج البلاغۃ،الجزء الرابع:۵۴۲)
۶۹۔سب سے بڑی مال داری امید کو خیربادکہنا ہے۔
۷۰۔جس کی امید لمبی ہوگی اس کا عمل خراب ہوجائے گا۔
(نھج البلاغۃ،الجزء الرابع:۵۴۵)
۷۱۔اگر نفلی عبادت فرائض میں نقصان کا سبب بن رہی ہوں تو ایسے نوافل سے ثواب حاصل نہ ہوگا۔
(نھج البلاغۃ،الجزء الرابع:۵۴۶)
۷۲۔وہ گناہ جو آپ کو غمگین کردے اس نیکی سے بہتر ہے جو آپ کو عجب اورخود پسندی میں مبتلا کردے۔
(نھج البلاغۃ،الجزء الرابع:۵۴۷)
۷۳۔سخاوت تو وہ ہے جو بن مانگے عطا کیا جائے،جو چیز مانگ کر دی جائے وہ حیاء اورشرمندگی سے بچنے کے لئے ہے۔
۷۴۔عقل جیسی مالداری نہیں،جہالت جیسی ناداری نہیں،ادب جیسی میراث کوئی نہیں اورمشورہ جیسی دانش مندی کوئی نہیں۔
۷۵۔صبردو طرح کا ہوتا ہے،ایک وہ صبر جو کسی ناگوار صورت کے پیش آنے پر کیا جائے اور دوسرا وہ صبر جو کسی محبوب چیز سے محرومی پر کیا جائے۔
(نھج البلاغۃ،الجزء الرابع:۵۴۸)
۷۶۔مال تمام شہوات کا مادہ اور بنیاد ہے۔
۷۷۔زبان ایک درندہ ہے،اگر اسے آزاد چھوڑدیا جائے تو ہلاک کردے گا۔
(نھج البلاغۃ،الجزء الرابع:۵۴۸)
۷۸۔محبوب لوگوں کو کھودینا انسان کو وطن میں بھی پردیسی بنادیتا ہے۔
۷۹۔جب عقل کامل ہوجاتی ہے تو کلام کم ہوجاتا ہے۔
(نھج البلاغۃ،الجزء الرابع:۵۴۹)
۸۰۔مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اللہ تعالی کی رحمت سے ناامید ہوبیٹھا ہے ؛حالانکہ اس کے پاس استغفار موجود ہے،جس کے ذریعے وہ اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے۔
۸۱۔جوشخص اپنے اور اللہ تعالی کے تعلق کو درست کرلےگا اللہ تعالی اس کے اور لوگوں کے تعلق کو درست کردے گا،جوشخص آخرت کے معاملہ کو درست کردے گا اللہ تعالی اس کی دنیا کے معاملہ کی اصلاح فرمادے گا۔
(نھج البلاغۃ،الجزء الرابع:۵۵۲)
۸۲۔کامیاب فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کرے ،اور انہیں اللہ کے عذاب سے مامون نہ کرے۔
(نھج البلاغۃ،الجزء الرابع:۵۵۳)
۸۳۔تقویٰ کے ساتھ تھوڑا عمل بھی بہت ہے،جو چیز قبول ہوجائے وہ تھوڑی کیسے ہوسکتی ہے۔
۸۴۔اللہ تعالی پر یقین کے ساتھ سوجانا شک کی نماز سے بہتر ہے۔
(نھج البلاغۃ،الجزء الرابع:۵۵۴)
۸۵۔دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے،اس کاظاہر نرم وملائم اور دلکش ہے جبکہ اس کے اندر ہلاکت خیز زہر چھپا ہوا ہے،بےوقوف جاہل اس میں دلچسپی رکھتا ہے جب کہ سمجھدار اوردانش مند شخص اس سے دور بھاگتا ہے۔
(نھج البلاغۃ،الجزء الرابع:۵۵۹)
۸۶۔جس شخص کے دل میں خالق کی عظمت ہوتی ہے ساری مخلوق اس کی نگاہ میں چھوٹی ہوجاتی ہے۔
(نھج البلاغۃ،السحرہ الرابع:۵۶۱)
۸۷۔جسے چار چیزیں عطا کردی جائیں وہ چار چیزوں سے محروم نہیں ہوسکتا(۱)جسے دعا عطا کردی جائے وہ عطا سے محروم نہیں ہوتا۔(۲)جس توبہ عطا کردی جائے وہ قبولیت سے محروم نہیں ہوتا۔(۳)جسے استغفار عطا کردیا جائے وہ مغفرت سے محروم نہیں ہوتا۔ (۴)جسے شکر عطا کردیا جائے وہ زیادتی سے محروم نہیں ہوتا۔
(نھج البلاغۃ،الجزء الرابع:۵۶۲)
۸۸۔صدقہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرو۔
(نھج البلاغۃ،الجزء الرابع:۵۶۴)
۸۹۔اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں پر لے جانے والا اس شخص کو ملامت نہ کرے جو اس کے بارے میں بد گمانی کرتا ہے۔
۹۰۔فقر بڑی موت ہے۔
(نھج البلاغۃ،الجزء الرابع:۵۶۳)
۹۱۔لوگ جس چیز سے ناواقف ہوں اس کے دشمن ہوتے ہیں۔
۹۲۔سینہ کا کشادہ پن سرداری کا زینہ ہے۔
(نھج البلاغۃ،الجزء الرابع:۵۷۰)
۹۳۔جیسے جہالت کی بات کرنا خیر سے خالی ہے اسی طرح دانش مندی کی بات نہ کرنے میں بھی خیر نہیں۔
۹۴۔جسے صبر فائدہ پہنچاسکے اسے بے صبری ہلاک کردیتی ہے۔
(نھج البلاغۃ،الجزء الرابع:۵۷۱)
۹۵۔ہر برتن کی یہ حالت ہے کہ جب اس میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ تنگ ہوتا ہے،لیکن علم کا برتن ایسا ہے کہ جب اس میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے وہ کھلتا چلاجاتا ہے۔
(نھج البلاغۃ،الجزء الرابع:۵۷۴)
۹۶۔مختلف حالات کے الٹ پلٹ ہونے میں آدمی کے جواہر کا پتہ چلتا ہے۔
(نھج البلاغۃ،الجزء الرابع:۵۷۴)
۹۷۔لالچی ذلت کی بیڑیوں میں جکڑارہتا ہے۔
(نھج البلاغۃ،الجزء الرابع:۵۷۷)
۹۸۔اگر کوئی شخص آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے تو آپ اس کے گمان کو سچا کرکے دکھائیں۔
۹۹۔میں نے اللہ تعالیٰ کو ارادوں کے ٹوٹنے اور نیتوں کے بکھرنے سے پہچانا۔
(نھج البلاغۃ،الجزء الرابع:۵۸۰)
۱۰۰۔تمہارے دوست بھی تین ہیں اوردشمن بھی،تمہارے تین دوست یہ ہیں۔ (۱)تمہارا دوست (۲)تمہارے دوست کا دوست (۳)تمہارے دشمن کا دشمن،تمہارے تین دشمن یہ ہیں۔ (۱)تمہارا دشمن (۲)تمہارےدوست کا شمن(۳)تمہارے دشمن کا دوست
(نھج البلاغۃ،الجزء الرابع:۵۹۴)
۱۰۱۔غیرت مند آدمی کبھی زنا نہیں کرتا۔
۱۰۲۔موت بہترین پہرے دار ہے۔
۱۰۳۔آدمی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوسکتا جب تک اللہ تعالی کے خزانوں پر اس کا اعتماد اپنے پاس موجود چیزوں سے زیادہ نہ ہوجائے۔
۱۰۴۔تنہائیوں میں گناہ کرنے سے بچو؛ کیونکہ جو تمہیں دیکھ رہا ہے فیصلہ اسی کو کرنا ہے۔
(نھج البلاغۃ،الجزء الرابع:۵۹۸)
۱۰۵۔ہرآدمی کے مال میں دوشریک ہوتے ہیں ایک وارث اوردوسرا حوادثات زمانہ۔
(نھج البلاغۃ،الجزء الرابع:۶۰۰)
۱۰۶۔کسی کے استحقاق سے بڑھ کر اس کی تعریف کرنا خوشامد ہے اور استحقاق سے کم تعریف کرنا حسد۔
(نھج البلاغۃ،الجزء الرابع:۶۰۱)
۱۰۷۔بغیر عمل کے دعوت دینے والا ایسے ہے جیسے بغیر کمان کے تیر پھینکنے والا۔
(نھج البلاغۃ،الجزء الرابع:۶۰۰)
۱۰۸۔کسی کی زبان سے برائی کا کوئی کلمہ نکلے تو اس کے بارے میں اس وقت تک بد گمانی نہ کرو جب تک اس کی بات میں بھلائی کا احتمال موجود ہے۔
۱۰۹۔علم عمل کے ساتھ ملا ہوا ہے،پس جو علم حاصل کرے وہ عمل بھی کرے، علم عمل کی طرف پکارتا ہے اگر اس کی پکار سن لی جائے تو وہ ٹھہرجاتا ہے اور اگر اس کی پکار پر لبیک نہ کہا جائے تو علم رخصت ہوجاتا ہے۔
(نھج البلاغۃ،الجزء الرابع:۶۰۴)
۱۱۰۔بخل تمام خرابیوں کو جمع کرنے والا ہے،یہ ایک لگام ہے جس کے ذریعہ انسان کو تمام خرابیوں کی طرف ہنکایا جاسکتا ہے۔
۱۱۱۔جب آدمی کسی چیز کی طلب کرتا ہے تو وہ اسے مل ہی جاتی ہے اگر ساری نہ بھی ملے تو کچھ نہ کچھ تو ہاتھ آہی جاتا ہے۔
۱۱۲۔وہ خیر کوئی خیر نہیں جس کے بعد جہنم ہے اور وہ شر کوئی شر نہیں جس کے بعد جنت ہے،دنیا کی ہر نعمت جنت کے مقابلہ میں حقیر ہے اوردنیا کی ہر مصیبت جہنم کی مصیبتوں کے مقابلہ میں عافیت ہے۔
(نھج البلاغۃ،الجزء الرابع:۶۱۰)
۱۱۳۔جو دنیا مل جائے وہ لے لو اور دنیا کی جو چیز تم سے دورہے تم بھی اس سے دور رہو۔
(نھج البلاغۃ،الجزء الرابع:۶۱۱)
۱۱۴۔جو حق سے مقابلہ کرے گا حق اس کو پچھاڑ کر رکھ دے گا۔
(نھج البلاغۃ،الجزء الرابع:۶۱۲)
۱۱۵۔رزق کی دو قسمیں ہیں ایک رزق طالب ہے اوردوسرا رزق مطلوب ہے،جو شخص دنیاکو طلب کرتا ہے موت اس کی طالب بن جاتی ہے،یہاں تک کہ اسے دنیا سے نکال دیتی ہے اور جو شخص آخرت کا طالب بن جاتا ہے دنیا اس کی طالب بن جاتی ہے،یہاں تک کہ اسے اپنا رزق ضرورت کے مطابق مل جاتا ہے۔
(نھج البلاغۃ،الجزء الرابع:۶۱۶)
۱۱۶۔جو چھوٹی مصیبتوں پر صبرنہ کرے اللہ تعالیٰ اسے بڑی آزمائشوں میں مبتلا کردیتے ہیں۔
۱۱۷۔انسان کا کیا فخر کرنا ؟ اس کی ابتداء ناپاک پانی ہے اورانتہاء مردار لاش ہے،نہ اپنا رزق خود پیدا کرسکتا ہے اورنہ اپنی موت کو دور کرسکتا ہے۔
(نھج البلاغۃ،الجزء الرابع:۶۱۹)
۱۱۸۔سب سے خطرناک گناہ وہ ہے جسے اس کا کرنے والا ہلکا سمجھے۔
۱۱۹۔بدترین دوست وہ ہے جس کے لئے تکلف کرنا پڑے۔
۱۲۰۔جب کسی مومن کو اس کا بھائی شرمندہ کرے یا غصہ دلائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی جدائی کا وقت قریب آگیا ہے۔
(نھج البلاغۃ،الجزء الرابع:۶۲۴)
۱۲۱۔عقل مند اپنے آپ کو پست کرکے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کوبڑھاکرذلت اٹھاتا ہے۔
۱۲۲۔دوستی ایک خود پیدا کردہ رشتہ ہے۔
۱۲۳۔گناہوں پر نادم ہونا ان کو مٹادیتا ہے اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کردیتا ہے۔
۱۲۴۔بے کاری میں عشق بازی یاد آجاتی ہے۔
۱۲۵۔معافی نہایت اچھا انتقام ہے۔
۱۲۶۔غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔
۱۲۷۔تجربے کبھی ختم نہیں ہوتے اور عقل مند ان میں ترقی کرتا ہے۔
۱۲۸۔مصیبت میں گھبرانا کمال درجے کی مصیبت ہے۔
۱۲۹۔جلدی سے معاف کرنا انتہائے شرافت اور انتقام میں جلدی کرنا انتہائے رذالت ہے۔
۱۳۰۔شریف کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی سختی کرے تو سختی سے پیش آتا ہے اورجب کوئی نرمی کرے تو ڈھیلا ہوجاتا ہے اورکمینے سے جب کوئی نرمی کرےتو سختی سے پیش آتا ہے اور جب سختی کرے تو ڈھیلا ہوجاتا ہے۔
۱۳۱۔انسان جوحالت اپنے لئے پسند کرتا ہے اسی حالت میں رہتا ہے۔
۱۳۲۔بُرا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھتا؛ کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا گمان کرتا ہے۔
۱۳۳۔جب تک کوئی بات تیرے منہ میں ہے تب تک تو اس کا مالک ہے،جب زبان سے نکال چکا تو وہ تیری مالک ہے۔
۱۳۴۔اول عمر میں جو وقت ضائع کیا ہے آخر عمر میں اس کا تدارک کر؛تا کہ انجام بخیر ہو۔
۱۳۵۔جس شخص کے دل میں جتنی زیادہ حرص ہوتی ہے اس کو اللہ تعالی پر اتنا ہی کم یقین ہوتا ہے۔
Jan 16 2015
(۳) کھانا اتنا کھانا چاہئے جس سے زندگی قائم رہے۔
(۴) کپڑے پہننے میں نمائش باعثِ عذاب ہے۔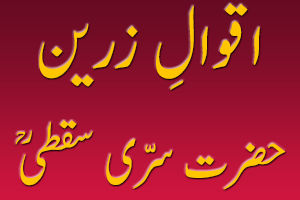
(۵) رہائش کے لئے محلات بنانے سے جنت نہیں مل سکتی۔
(۶) وہ علم بیکار ہے جس پر عمل نہ کیا ہو۔
(۷) مومن وہ ہے جو کاروبار زندگی میں بھی یادِ الٰہی سے غافل نہ ہو۔
(۸) کاش تمام مخلوقات کا غم میرے دل پر ہوتا تاکہ سب فارغ البال ہوتے۔
(۹) اگر کوئی اپنے ادب سے عاجز آتا ہے تو دوسروں کے ادب سے ہزار بار عاجز آتا ہے۔
(۱۰) تم کو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جن کا فعل ان کے قول سے مطابق نہیں رکھتا، مگر بہت کم ایسے بھی ملیں گے جن کا فعل و عمل ان کی زبان سے عین مطابق ہو۔
(۱۱) سب سے بڑا دانشور وہ ہے جو کلام اللہ شریف کی آیات مبارکہ پر غور و فکر کرے اور ان سے تدبر و تفکر کو کام میں لائے۔
(۱۲) جو اپنے نفس کا طیع ہوجاتا ہے اس کے لئے تباہی کے سواء کچھ نہیں ہے۔
(۱۳) جو شخص اپنے آپ کو بلند مرتبہ کہلوانا پسند کرے نگاہِ حق سے گرجاتا ہے
(۱۴) حسنِ خُلق یہ ہے کہ خلقت تجھ سے راضی ہو۔
(۱۵) محض گمان پر کسی سے علاحدگی اختیار مت کرو۔
(۱۶) بغیر عتاب کے کسی کی صحبت مت چھوڑو۔
(۱۷) اس شخص سے بچو جو باعزت ہو کر مجلس میں بیٹھے اور بے عزت ہوکر نکالا جائے۔
(۱۸) عشق حقیقی تو وہ ہے جو جذبہ عمل کو تیز کردے۔
(۱۹) حق پر چلنے والے کا پاؤں شیطان کے سینہ پر ہوتا ہے۔
(۲۰) علم کی مثال سمندر جیسی ہے خواہ کتنا ہی خرچ کرو کم نہ ہوگا۔
(۱)جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا دین سالم رہے اور اس کا بدن آرام سے رہے اور رنج و غم میں ڈالنے والے کلام کے سننے سے بچا رہے تو اس کو چاہئے کہ لوگوں سے الگ تھلگ ہوجائے اس لئے کہ یہ زمانہ عزلت اور وحدت کا ہے ۔
(۲)سب سے بڑی قوت یہ ہے کہ تم اپنے نفس پر غالب آجاؤ اور جو شخص اپنے نفس کی تادیب سے عاجز ہے تو پھر اپنے غیر کی تادیب سے بدرجہ اولیٰ عاجز ہوگا ۔
(۳)تین چیزیں اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی علامت ہیں : لہو و لعب کی کثرت ، ہنسی مذاق اور غیبت و شکایت ۔
Jan 13 2015
سیدنا حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے ایک بلند پایہ عالم دین تھے، آپ عالم، محقق، عاملِ صدیق، میوۂ باغِ اولیاء تھے، آپ جامع کمالات، پیشوائے مشائخ اور بے شمار کتابوں کے مصنف تھے۔
(۱) عبادت بلا توبہ درست نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو عبادت پر مقدم کیا ہے۔
(۲) دروغ گو کو مروت نہیں ہوتی۔
(۳) حاسد کو راحت اور بدخلق کو سرداری نہیں ملتی۔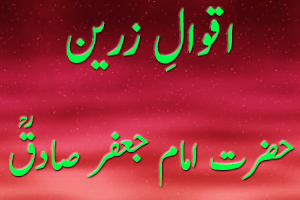
(۴) اپنے آپ کو محرکات الٰہی سے بچاؤ تاکہ عابد بنو اور جو کچھ قسمت میں لکھا ہے اس پر صبر کرو۔
(۵) درویش صابر‘ تونگر شاکر سے افضل ہے، کیونکہ تونگر کا دل کینہ میں لٹکا رہتا ہے اور درویش کا دل اللہ تعالیٰ سے لگا رہتا ہے۔
(۶) فاجر سے صحبت مت رکھ کہ تجھ پر فجور غالب آجائے گا۔
(۷) جو کوئی اللہ تعالیٰ سے انس رکھتا ہے، اسے خلق سے وحشت ہوجاتی ہے۔
(۸) جو شخص ہر کس و ناکس کے ساتھ صحبت رکھتا ہے وہ سلامت نہیں رہتا۔
(۹) لوگ خود غرضیوں اور فریبوں کے درمیان الجھے ہوئے آپس میں محبت اور وفا کا اظہار کررہے ہیں، حالانکہ ان کے دل بچھوؤں سے بھرے ہیں۔
(۱۰) عاقل وہ ہے جو خیر و شر میں تمیز کرے۔
(۱۱) دنیا میں ہی بہشت اور دوزخ ہے، بہشت عافیت ہے اور دوزخ بلاعافیت یہ ہے، اچھے کاموں میں مصروف رہ کر ان کے نتیجہ کو خدا پر چھوڑدو، بلا یہ ہے کہ حق کا لحاظ نہ رکھ کر اپنے کاروبار کو صرف نفس کے خواہشوں پر کرو۔
(اقوال کا خزانہ)
(۱)چار چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے کسی شریف کو کراہت کرنی زیبا نہیں : اپنے باپ کے لئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہونا ، اپنے مہمان کی خدمت کرنا ، اپنی سواری کے جانور کی خود نگہداشت کرنا اگر چہ اس کے سیکڑوں غلام اور نوکر کیوں نہ ہوں ، اور جس سے علم حاصل کر رہا ہے اس کی خدمت کرنا ۔
(۲)نیکی کامل نہیں ہوتی مگر تین باتو ں سے ایک یہ کہ جب اس کو کرو تو اس کو چھوٹی سمجھو ، دوسرے یہ کہ اس کو پوشیدہ رکھو ، تیسرے یہ کہ اس میں عجلت کرو ، کیونکہ جب تم اس کو حقیر سمجھو گے تو وہ بڑی ہوجائے گی ، اور جب اس کو چھپاؤگے تو اس کو کامل طور سے ادا کرسکوگے ، اور جب اس میں جلدی کروگے تو خوشگوار بنانے کی سعی کروگے ۔
(۳)جب کسی آدمی کی طرف دنیا توجہ کرتی ہے تو غیروں کی خوبیاں بھی اس کو دے دیتی ہے یعنی وہ آدمی خوشنما معلوم ہونے لگتا ہے ، اور جب اس سے منہ پھیرتی ہے تو اس کی ذاتی خوبیاں بھی لے لیتی ہے یعنی لوگوں کی نظروں میں بدنما ہوجاتا ہے ۔
(۴)جب تم کو اپنے بھائی کی کوئی ایسی بات پہونچے جو تم کو ناگوار ہو تو کہو کہ شاید اس کے پاس کوئی عذر ہو جس کو میں نہیں جانتا ۔
(۵)جب تم کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات سنو تو جہاں تک تمہاری قدرت ہو اس کو عمدہ پہلو پر ڈھالو یہاں تک کہ اگر کوئی عمدہ پہلو تم کو نہ ملے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرو ۔
(۶)جب تم سے گناہ سرزد ہو تو استغفار کرو کیونکہ پیدا ہونے کے پہلے ہی سے گناہ طوق بن کر لوگوں کے گلے میں پڑا ہوا ہے ، یقیناً پوری ہلاکت تو بس اس گناہ پر اصرار کرنا ہے ۔
(۷)جس کو روزی ملنے میں تاخیر ہو اس کو کثرت سے استغفار پڑھنا چاہئے اور جس کو اپنا کومال پسند ہو اور وہ اس کو باقی رکھنا چاہتا ہو تو “ماشاء اللہ لاقوۃ الا باللہ” کہنا چاہئے ۔
Jan 13 2015
۱۔میدوں کو لمبا مت کرو اورقیامت کو دور نہ سمجھو؛کیونکہ جو مرگیا اس کی قیامت قائم ہوگئی۔
(روضۃ الخطباء:۴۴۰)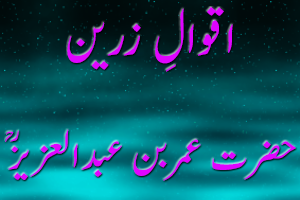
۲۔سنت کی مخالفت کرکے سلامتی حاصل نہیں ہوسکتی اوراللہ تعالی کو ناراض کرکے مخلوق کی رضا حاصل نہیں کی جاسکتی۔
(روضۃ الخطباء:۴۴۰)
۳۔دنیا ایک دیمک زدہ امید کا نام ہے،گزرجانے والی گھڑی سے عبارت ہے،آخرت کی طرف جانے کا راستہ ہے اور موت کی طرف پہنچانے کا ذریعہ ہے،اللہ تعالی اس شخص پر رحم کرے جو حقیقت پر نگاہ رکھے،اپنے نفس کی خیر خواہی کا فیصلہ کرے،اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے،گناہوں سے احتراز کرے اوراپنے دل کو نورانی بنائے۔
۴۔تم جانتے ہو کہ تمہارے والد(حضرت آدم علیہ السلام)ایک لغزش کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے تھے،پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی وجہ سے ان کی لغزش کی معافی کا وعدہ فرمایا تھا،پس تم اپنے گناہوں سے ڈرتے رہو اوراپنے رب سے معافی کی امید رکھو۔
۵۔کوئی شخص اس قابل نہیں کہ اللہ تعالی کو ناراض کرکے اس کی اطاعت کی جائے۔
۶۔یادرکھو !سب سے افضل عبادت فرائض کی ادائیگی اورحرام کاموں سے بچنا ہے۔
(روضۃ الخطباء:۴۰۹)
۷۔ایک دن سلیمان بن عبدالملک کے دل میں اپنی بادشاہت کے عروج پر تفاخر اورعجب پیدا ہوا،اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ سے پوچھا کہ اس عروج وارتقاء کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے فرمایا:
“یہ خوشی کی چیز ہے اگر اس میں دھوکہ کی آمیزش نہ ہو،یہ بہت بڑی نعمت ہے بشرطیکہ اس کو زوال نہ ہو،بادشاہت ہے اگر اس کو برباد نہ ہونا ہو،مسرت ہے اگر اس کے بعد رنج نہ ہو،یہ لذتیں ہیں اگر ان کے بعد آفات کا سامنا نہ کرنا پڑے اورشرافت کی چیز ہے اگر اس کے ساتھ سلامتی مل جائے”۔
یہ سن کر سلیمان بن عبداملک اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہوگئی۔
(نفحۃ العرب:۱۳۰)
۸۔ایک مرتبہ حج کے موقع پر سلیمان بن عبداملک نے عمر بن عبدالعزیز ؓ سے کہا کہ کیا تم اس لاتعداد مخلوق کو دیکھتے ہو جسے اللہ تعالی کے سوا کوئی شمار نہیں کرسکتا اور اس کے علاوہ کوئی رزق نہیں دے سکتا،حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے فرمایا:
“اے امیر مؤمنین!آج یہ آپ کی رعیت ہیں لیکن کل اللہ تعالی کے دربار میں آپ کے مد مقابل ہوں گے”یہ سن کر سلیمان بہت رویا اورکہا میں اللہ تعالی سے مدد کا خواستگار ہوں۔
(نفحۃ العرب:۱۲۹)
۹۔قبر ہر ایک کو پکارتی ہے،ہر ایک کو پیغام دیتی ہے،ہر ایک کو ہر روز اپنے بارے میں بتاتی ہے،وہ نہایت فصیح اور صاف آواز کے ساتھ یہ اعلان کرتی ہے‘‘اے ابن آدم!تو مجھے بھول گیا، میں تنہائی کا گھر ہوں،میں اجنبیت کا گھر ہوں،میں دہشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں نہایت تنگی کا گھر ہوں،مگر اس شخص کے لئے نہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے وسیع کردیا۔
(البدایۃ والنھایۃ:۹/۱۰۴)
۱۰۔ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ کو سیب اور دوسرے میوہ جات ہدیہ میں بھیجے،آپ نے واپس کردیئے،بھیجنے والے نے کہا رسول اللہ ﷺ تو ہدیہ قبول کرلیا کرتے تھے۔
حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے جواب دیا:
((ان الحدیۃ کانت لہ ھدیۃ،وھی الیوم لنا رشوۃ))
“ہدیہ آپ ﷺ کے لئے ہدیہ ہوتا تھا لیکن آج ہمارے لئے رشوت ہے”
(سیرأعلام النبلاء:۵/۱۴۰)
یعنی لوگ ہمیں ہدیہ دے کر ہم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم سے اپنے کام نکلوائیں گے۔
۱۱۔لوگوں نے جو بدعت بھی ایجاد کی ہے سنت رسول اللہﷺ میں اس کی قباحت اور برائی کی دلیل موجود ہے یا اس میں خود عبرت ہے اس لئے کہ طریق سنت کو اس ذات حق تعالیٰ نے جاری کیا ہے جس نے پہلے یہ معلوم کرلیا تھا کہ اس طریق کے خلاف میں خطاو لغزش ،حماقت اورتکلیف ہے۔
(سنن أبی داؤد:۲/۲۸۵)
۱۲۔صحابہ کرامؓ معاملات دین میں اتنا کلام کرچکے ہیں جو بالکل کافی ہے اور اس کو اتنا بیان کردیا ہے جو شفا دینے والا ہے،پس ان کے طریقہ سے کمی وکوتاہی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں اوران سے زیادتی کرنے کا بھی کسی میں حوصلہ نہیں اور بہت سے لوگوں نے ان کے طریقہ سے زیادہ کا ارادہ کیا وہ غلو میں مبتلا ہوگئے اور یہ حضرات افراط وتفریط اور کوتاہی کے درمیان ایک راہ مستقیم پر تھے۔
(سنن ابی داؤد:۲/۲۸۵)
۱۳۔اسلاف جو قیل و قال سے بچے ہیں وہ علم کی وجہ سے بچے (نہ کہ عجز وناواقفیت سے)اورمکمل بصیرت پر انہوں نے لوگوں کو قیل و قال سے روکا ہے اوراگر وہ بحث کرنا چاہتے تو وہ سب سے زیادہ اس پر قادر تھے۔
(ثمرات الاوراق:۲۱۵)
۱۴۔اس قیاس کو اختیار کرو جو تم سے پہلے حضرات(صحابہ)کی رائے کے موافق ہوکیونکہ وہ لوگ تم سے زیادہ علم والے تھے۔
(فضل علم السلف لابن رجب:۲۰)
۱۵۔مجھے ہرگز یہ پسند نہیں کہ صحابہ کرامؓ میں مسائل فروعیہ کا اختلاف نہ ہوتا کیونکہ اگر ایک ہی قول ہوتا تو لوگ تنگی میں پڑجاتے،یہ حضرات مقتداء اورپیشوا ہیں جو شخص ان میں سے کسی کے مذہب پر عمل کرے، اس کے لئے اس کی گنجائش ہے۔
(جامع بیان العلم:۱۴۳)
۱۶۔ایک مرتبہ کسی نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ سے حضرت علیؓ اورحضرت معاویہؓ کی باہمی جنگ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا:
((دماء ظھر اللہ عنھا سیوفنا افلا نظھر عنھا السنتنا))
“یہ وہ خون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا ہے تو اب ہم اپنی زبانوں کو اس خون سے آلودہ کرلیں”
(حیوۃ الحیوان:۱/۳۸۴)
۱۷۔جب عمر بن عبدالعزیزؓ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنا سارا مال بانٹ دیا،لوگوں نے کہا کہ اپنے بچوں کے لئے کچھ نہیں چھوڑا تو فرمایا:
“اگرمیری اولادصالح ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے “واللہُ وَلِیُّ الْمُؤْمِنِیْنَ” اللہ تعالیٰ مؤ منین کا کارساز ہے اوراگر غیر صالح ہے تو میں ان پر اپنے پیسے کو ضائع نہیں کرنا چاہتا”
(البدایۃ والنھایۃ:۹/۲۰۰)
۱۸۔میں نے حاسد سے بڑھ کر کسی ظالم کو مظلوم کے ساتھ زیادہ مشابہ نہیں دیکھا؛کیونکہ حاسد کو ہمیشہ غم رہتا ہے۔
(الرسالۃ القشیریۃ:۲۱۴)
(۱)اگر موت سے غفلت نہ ہوتی تو تمام مخلوق خوف ِ الٰہی سے مرجاتی۔
(۲)مؤمن کی قوت دل میں ہوتی ہے اور کافر و منافق کی طاقت ہاتھ میں ۔
(۳)اپنی آرزوؤں کو دل میں ہی مار ڈالو ، اور دلوں کو ان میں نہ مرنے دو، کیونکہ جس نے اپنی شہوات کو پاؤں کے نیچے دبایا ، شیطان اس کے سایہ سے بھی بھاگتا ہے ، اور وہ شخص جو خواہشات کو دل میں جگہ دے تو شیطان اس پر سوار ہوجاتا ہے اور جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس پر مسلط کردیتے ہیں۔
(۴)آپ سے نصیحت کی درخواست کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس بات سے ڈر! کہ تو صالحین کا ہمنشین ہو اور ان سے فائدہ نہ اٹھائے ، یا تو گنہگاروں کو برا کہے اور خود گناہوں سے پرہیز نہ کرے ، یا علانیہ شیطان کو لعنت کرے اور باطن میں اس کا مطیع ہو ۔
(۵)تم میں سے کوئی بھی متقی نہیں ہوسکتا جب تک ہر ایسا قول و فعل ترک نہ کردے جس سے دنیا اور آخرت میں فضیحت اور شرمندگی ہو ۔
(۶)آپ سے عرض کیا گیا انسان تقویٰ کی چوٹی پر کب پہونچ سکتا ہے ؟ فرمایا جب اپنے تمام خیالات کو طباق میں رکھ کر بازار میں چکّر لگائے اور شرمندہ نہ ہو ۔
(۷)تقویٰ یہ نہیں کہ دن بھر روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے اور نیک و بد اعمال کو خلط ملط کرے بلکہ تقویٰ یہ ہے کہ محرمات الٰہی کو چھوڑدے اور فرائض ادا کرے جو اس سے بڑھ کر کرے وہ نورٌ علیٰ نور ہے ۔
(۸)متقی کی علامت یہ ہے کہ وہ کلام کرنے سے لگام لگایا گیا ہو ، جیسے احرام کی حالت میں محرِم ، نیز متقی کو تمام شریعت کا عالم ہونا ضروری ہے ، ورنہ اپنی جہالت سے تقویٰ کی حدود سے نکل جائےگا اور اسے خبر تک نہ ہوگی
Jan 29 2015
Allah is everywhere – Sufi Sahab Rahmath ullah Alaih
Allah is everywhere – Sufi Sahab Rahmath ullah Alaih
ارشاد :- سلطان العارفین حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحبؒ
نحمدہ و نصلی علٰی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالٰی ہمارے خالق، مالک، حاکم، رب اور معبود ہیں۔ اس لئے الہ ہیں ۔ ایک سوال کہ جن کو ہم نے یہ سب یعنی “خالق، مالک، حاکم،رب، معبود” مانا ہے، کہاں ہے؟ سوال کرنے والے سب سن لیں اور توجہ سے سنیں ۔ اللہ تعالٰی نے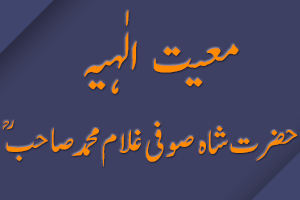 فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ ارشاد ہوا بے شک میں قریب ہوں۔ مجھ جیسےمعمولی سمجھ والے کے لئے یہ کافی ہے۔ پتہ مل گیا۔لیکن کچھ شعور والا بھائی ہو تو اس سے مطمئن نہں ہوگا۔ یہ سوال تو آئیگاکہ قریب تو ہیں لیکن کتنے قریب؟ اس تقاضہ کا، اس سوال کا جواب ارشاد ہوا۔ “نحن اقرب الہی من حبل الورید” ہم اسکی رگِ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اپنی جان کو دیکھ لیا؟ دیکھ لیا۔ تجھ سے تیری جان جتنی قریب ہے ہم اس سے زیادہ قریب ہیں ۔ اب پتہ مل گیا، راز کھل گیا۔ اطمنارن ہوگیا ۔ لیکن یہ حضرتِ انسان ہیں، پھر بھی اطمینان نہیں۔ پھر سوال ہوا کہ کب کب اقرب رہتے ہیں؟ نماز میں؟ مراقبہ میں؟ مشاہدہ میں؟ کب کب؟۔
فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ ارشاد ہوا بے شک میں قریب ہوں۔ مجھ جیسےمعمولی سمجھ والے کے لئے یہ کافی ہے۔ پتہ مل گیا۔لیکن کچھ شعور والا بھائی ہو تو اس سے مطمئن نہں ہوگا۔ یہ سوال تو آئیگاکہ قریب تو ہیں لیکن کتنے قریب؟ اس تقاضہ کا، اس سوال کا جواب ارشاد ہوا۔ “نحن اقرب الہی من حبل الورید” ہم اسکی رگِ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اپنی جان کو دیکھ لیا؟ دیکھ لیا۔ تجھ سے تیری جان جتنی قریب ہے ہم اس سے زیادہ قریب ہیں ۔ اب پتہ مل گیا، راز کھل گیا۔ اطمنارن ہوگیا ۔ لیکن یہ حضرتِ انسان ہیں، پھر بھی اطمینان نہیں۔ پھر سوال ہوا کہ کب کب اقرب رہتے ہیں؟ نماز میں؟ مراقبہ میں؟ مشاہدہ میں؟ کب کب؟۔
جواب آیا “وھومعکم این ماکنتم” تو جہاں ہے وہیں ہوں۔ تو زمین پر ہے تو میں تیرے ساتھ، تو عبادت میں ہے تو میں تیرے ساتھ، تو معصیت میں ہے تو میں تیرے ساتھ۔ اور کچھ پوچھنا ہے؟ ایک اور بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میرے ساتھ کیسے؟ تو سنو ! ” خبردار! ہوشیار ! دل کی آنکھ کھول کر بات سنو! ہوش سے سنو! “ ألا إنه بكل شيء محيط” پھر پوچھا کیسے محیط ہیں؟ اندر یا باہر؟ نیچے یا اوپر؟ آگے یا پیچھے؟ تو سنو! تمہارے اندر، باہر، نیچے، اوپر، آگے اور پیچھے ہم محیط ہیں۔ اب سوالات کے فطری تقاضے ختم ہوئے۔ اب میری طرف سے انعام کے طور پر سنو! “ھوالاول والآخر والظاھر والباطن وھو بکل شی محیط” اب فکرِ انسانی کوئی سوال اٹھا سکتی ہے تو اٹھائے۔ یہ فضل و کرم ہے، نوازش ہے۔ میں تیرا اول و آخر ظاہر و باطن! ہاں! یہی وہ مقام ہے جہاں بعض مشأیخین و صوفیا بھی چکر کھا رہے ہیں۔یُضِلُّ بِه مَنْ یَّشَآءُ کی تجلی نظر آرہی ہے۔ قرآن کی اسی آیت کو پڑھ کر دوزخ کا ایندھن بنتے جارہے ہیں۔
دل کی نمازیں، ھو حق کے نعرے چل رہے ہیں۔ تو کون ہے؟ جواب ملیگا “میں شئے ہوں”۔ تو فرمایا میں شئے کا اول و آخر اور ظاہر و باطن ہوں۔ اگر شئے ہی نہ ہو تو کس کے اول؟ کس کے آخر؟ کس کے ظاہر؟ کس کے باطن؟ پتہ بتا دیا۔ پوری پوری ہدایت بینہ ہے۔ واضح حقأیق ہیں۔ شئے کا علم دے کر یہ سارے اعتبارات کھولے گئے۔ اللہ علیم، اور شئے “معلوم”۔ ماشأاللہ! اگر شئے ہی نہیں ہے تو اولیت و آخریت، ظاہریت و باطنیت بے معنی ہو جأیں ہر بال شئے، اسکے اول و آخر ظاہر باطن اللہ۔ خون کا ہر قطرہ شئے، اس کے اول و آخر ظاہر باطن اللہ۔ شیطان سئے، اس کے اول آخر ظاہر باطن اللہ۔ جنت شئے، اس کے اول آخر ظاہر، باطن اللہ، دوزخ شئے، اس کے اول آخر ظاہر باطن اللہ دل چپ نہیں رہتا اس لئے کہ پوچھنے والے کا نام ہی دل ہے۔ اللہ تعالٰی آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
By silsilaekamaliya • Bayanaat Hazrath Sufi Sahab R.A, Important Articles, Taleemat Silsila e Qadria Kamalia • Tags: Shah Sufi Sahab R.A, taleemat silsila e qadria